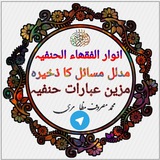پگڑی پر دوکان لینا دینا
بسم اللہ الرحمن الرحیم
الجواب حامدًا ومصلّياً
پگڑی کا معاملہ شرعاً ناجائز ہے اور پگڑی کے نام پر اصل مالک کو جو رقم دی جاتی ہے شرعاً وہ رشوت کے حکم میں ہے ، اور رشوت کا لینا اور دینا حرام ہے ، لہٰذااگر کسی نے پگڑی کا معاملہ کیا ہو تو اس معاملہ کو ختم کرنا اور آئندہ اس قسم کے معاملہ سے اجتنا ب کرنالازم ہے جسکی صورت یہ ہے کہ پگڑی پر دوکان لینے والا شخص دکان اصل مالک کو واپس کرے اور اصل مالک پگڑی کے نام پر لی جانے والی رقم پگڑی پر جائیداد لینے والے شخص کو واپس کرے ۔البتہ اگر کرایہ دارنے اس دوکان میں کسی تعمیر وغیر ہ کے ذریعہ سے کوئی قابلِ قدر اضافہ کیا ہوا یا واپسی کے وقت اضافہ کرلے تو وہ اس اضافہ کے عوض مالک سے پگڑی کی اصل رقم کے ساتھ اضافی رقم بھی وصول کرسکتا ہے۔
پگڑی کے معاملہ کو ختم کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جس نے پگڑی پر دوکان لی ہو وہ مالک سے یہ دوکان باہمی رضامندی سے قیمت طے کرکے باقاعدہ خرید لے اور اپنی ملکیت میں لےلے۔ اور اگر مالک یہ دوکان فروخت کرنے پر راضی نہ ہو تو نئے سرے سے کرایہ داری کاصحیح معاملہ بھی کرسکتے ہیں ، اس صورت میں کرایہ بھی باہمی رضامندی سے طے ہوگا،نیز اگر پگڑی کے متبادل کے طور پر درج ذیل صورت اختیار کرنا چاہیں تو کرسکتے ہیں:
اس دکان کو پچا س یا سو سال کی مدت کےلئے کرایہ پرلینے کا معاملہ کرلیا جائے اور کرایہ باہمی رضامندی سے ماہوار طے کرلیا جائے پھر کرایہ کا اکثر حصہ پیشگی دیدیا جا ئے اور باقی کرا یہ ماہواردینا طے ہوجائے مثلاًکرایہ دار پچاس سال کی مدت کےلئے یہ دوکان دو ہزار ماہوار کرایہ پر اصل مالک سے لے لے اور ایک ہزار روپے ماہوار کرایہ پچاس سال کا حساب لگا کر نقد پیشگی دیدے اور بقیہ ایک ہزار روپےکرایہ ہر ماہ اداکردے ،اگر دونوں فریق اس پر راضی ہوں تو یہ معاملہ باہمی رضامندی سے کیا جاسکتا ہے ۔ یہ صورت کے اختیار کرنے کے بعد اگر کرایہ دار کسی اور کو یہ دوکان کرایہ پر دینا چاہے تو پچاس سال کی مدت تک دے سکتا ہے اور اس عرصہ میں اپنے کرایہ داری کے حق سے دستبرداری کا معاوضہ بھی اس سے لے سکتا ہے،واضح رہے کہ یہ صورت کو اختیار کرنے کے بعد دوکان کا اصل مالک پچاس سال کی مدت سے پہلے کرایہ دارکو نکال نہیں سکتا۔(ماخذہ ، التبویب :١۴۵٦؛۳۳و ٧٠/٥٤٤)
بحوث في قضايا فقهية معاصرة (1 / 115):
تحقق مما ذكرنا أن بدل الخلو المتعارف الذي يأخذه المؤجر من مستأجره لا يجوز، ولا ينطبق هذا المبلغ المأخوذ على قاعدة من القواعد الشرعية، وليس ذلك إلا رشوة حراما. نعم: يمكن تعديل النظام الرائج للخلو إلى ما يلي: 1- يجوز للمؤجر أن يأخذ من المستأجر مقدارا مقطوعا من المال، يعتبر كأجرة مقدمة لسنين معلومة، وهذا بالإضافة إلى الأجرة السنوية أو الشهرية. وتجري على هذا المبلغ المأخوذ أحكام الأجرة بأسرها، فلو انفسخت الإجارة قبل أمدها المتفق عليه لسبب من الأسباب، وجب على المالك أن يرد على المستأجر مبلغا يقع مقابل المدة الباقية من الإجارة.
2- إذا كانت الإجارة لمدة معلومة استحق المستأجر البقاء عليها إلى تلك المدة، فلو أراد رجل آخر أن يتنازل المستأجر عن حقه، ويصير هو المستأجر بدله، يجوز للمستأجر الأول أن يطالب بعوض، ويكون ذلك نزولا عن حق الاستئجار بعوض، ويجوز ذلك قياسا على النزول عن الوظائف بمال. ولكن يشترط لذلك أن تكون الإجارة الأصلية إلى مدة معلومة كعشر سنين مثلا، ويتنازل المستأجر في أثنائها. 3- إذا كانت الإجارة لمدة معلومة، لا يجوز للمؤجر أن يفسخها إلا بمبرر شرعي، فإن أراد أن يفسخها دون مبرر شرعي، جاز للمستأجر أن يطالبه بعوض، ويكون ذلك نزولا عن حقه بعوض، وهذا بالإضافة إلى ما يستحقه من استرداد جزء باق من المبلغ المقطوع الذي دفعه المستأجر كأجرة مقدمة في بداية العقد…
واللہ اعلم بالصواب
نقلہ محمد مصروف مظاہری
@anwarulfuqaha
بسم اللہ الرحمن الرحیم
الجواب حامدًا ومصلّياً
پگڑی کا معاملہ شرعاً ناجائز ہے اور پگڑی کے نام پر اصل مالک کو جو رقم دی جاتی ہے شرعاً وہ رشوت کے حکم میں ہے ، اور رشوت کا لینا اور دینا حرام ہے ، لہٰذااگر کسی نے پگڑی کا معاملہ کیا ہو تو اس معاملہ کو ختم کرنا اور آئندہ اس قسم کے معاملہ سے اجتنا ب کرنالازم ہے جسکی صورت یہ ہے کہ پگڑی پر دوکان لینے والا شخص دکان اصل مالک کو واپس کرے اور اصل مالک پگڑی کے نام پر لی جانے والی رقم پگڑی پر جائیداد لینے والے شخص کو واپس کرے ۔البتہ اگر کرایہ دارنے اس دوکان میں کسی تعمیر وغیر ہ کے ذریعہ سے کوئی قابلِ قدر اضافہ کیا ہوا یا واپسی کے وقت اضافہ کرلے تو وہ اس اضافہ کے عوض مالک سے پگڑی کی اصل رقم کے ساتھ اضافی رقم بھی وصول کرسکتا ہے۔
پگڑی کے معاملہ کو ختم کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جس نے پگڑی پر دوکان لی ہو وہ مالک سے یہ دوکان باہمی رضامندی سے قیمت طے کرکے باقاعدہ خرید لے اور اپنی ملکیت میں لےلے۔ اور اگر مالک یہ دوکان فروخت کرنے پر راضی نہ ہو تو نئے سرے سے کرایہ داری کاصحیح معاملہ بھی کرسکتے ہیں ، اس صورت میں کرایہ بھی باہمی رضامندی سے طے ہوگا،نیز اگر پگڑی کے متبادل کے طور پر درج ذیل صورت اختیار کرنا چاہیں تو کرسکتے ہیں:
اس دکان کو پچا س یا سو سال کی مدت کےلئے کرایہ پرلینے کا معاملہ کرلیا جائے اور کرایہ باہمی رضامندی سے ماہوار طے کرلیا جائے پھر کرایہ کا اکثر حصہ پیشگی دیدیا جا ئے اور باقی کرا یہ ماہواردینا طے ہوجائے مثلاًکرایہ دار پچاس سال کی مدت کےلئے یہ دوکان دو ہزار ماہوار کرایہ پر اصل مالک سے لے لے اور ایک ہزار روپے ماہوار کرایہ پچاس سال کا حساب لگا کر نقد پیشگی دیدے اور بقیہ ایک ہزار روپےکرایہ ہر ماہ اداکردے ،اگر دونوں فریق اس پر راضی ہوں تو یہ معاملہ باہمی رضامندی سے کیا جاسکتا ہے ۔ یہ صورت کے اختیار کرنے کے بعد اگر کرایہ دار کسی اور کو یہ دوکان کرایہ پر دینا چاہے تو پچاس سال کی مدت تک دے سکتا ہے اور اس عرصہ میں اپنے کرایہ داری کے حق سے دستبرداری کا معاوضہ بھی اس سے لے سکتا ہے،واضح رہے کہ یہ صورت کو اختیار کرنے کے بعد دوکان کا اصل مالک پچاس سال کی مدت سے پہلے کرایہ دارکو نکال نہیں سکتا۔(ماخذہ ، التبویب :١۴۵٦؛۳۳و ٧٠/٥٤٤)
بحوث في قضايا فقهية معاصرة (1 / 115):
تحقق مما ذكرنا أن بدل الخلو المتعارف الذي يأخذه المؤجر من مستأجره لا يجوز، ولا ينطبق هذا المبلغ المأخوذ على قاعدة من القواعد الشرعية، وليس ذلك إلا رشوة حراما. نعم: يمكن تعديل النظام الرائج للخلو إلى ما يلي: 1- يجوز للمؤجر أن يأخذ من المستأجر مقدارا مقطوعا من المال، يعتبر كأجرة مقدمة لسنين معلومة، وهذا بالإضافة إلى الأجرة السنوية أو الشهرية. وتجري على هذا المبلغ المأخوذ أحكام الأجرة بأسرها، فلو انفسخت الإجارة قبل أمدها المتفق عليه لسبب من الأسباب، وجب على المالك أن يرد على المستأجر مبلغا يقع مقابل المدة الباقية من الإجارة.
2- إذا كانت الإجارة لمدة معلومة استحق المستأجر البقاء عليها إلى تلك المدة، فلو أراد رجل آخر أن يتنازل المستأجر عن حقه، ويصير هو المستأجر بدله، يجوز للمستأجر الأول أن يطالب بعوض، ويكون ذلك نزولا عن حق الاستئجار بعوض، ويجوز ذلك قياسا على النزول عن الوظائف بمال. ولكن يشترط لذلك أن تكون الإجارة الأصلية إلى مدة معلومة كعشر سنين مثلا، ويتنازل المستأجر في أثنائها. 3- إذا كانت الإجارة لمدة معلومة، لا يجوز للمؤجر أن يفسخها إلا بمبرر شرعي، فإن أراد أن يفسخها دون مبرر شرعي، جاز للمستأجر أن يطالبه بعوض، ويكون ذلك نزولا عن حقه بعوض، وهذا بالإضافة إلى ما يستحقه من استرداد جزء باق من المبلغ المقطوع الذي دفعه المستأجر كأجرة مقدمة في بداية العقد…
واللہ اعلم بالصواب
نقلہ محمد مصروف مظاہری
@anwarulfuqaha
*سوال: کیا عمامہ پگڑی جیسا بھی ہو سنت ہے یا کوئی خاص رنگ اور طریقہ ہے ؟*
الجواب حامدا ومصلیا
عمامہ کسی بھی رنگ کا ہو اس سے سنت ادا ہوجاتی ہے ۔اسی وجہ سے صحابہ سے مختلف رنگ کے عمامے استعمال کرنا ثابت ہے ،جن مین سیاہ ،سفید،پیلا،سبزاور سرخ رنگ شامل ہیں،البتہ رسول اللہ ﷺ سے صراحت کے ساتھ سیاہ رنگ کے عمامے کی روایات ملتی ہیں اور کسی رنگ کے بارے میں ہمیں تلاش بسیار کے باوجود کوئی روایت نہیں ملی ۔ہاں سفید رنگ آپ ﷺ لباس میں پسند فرماتے تھے اور سفید رنگ کے کپڑے میں کفن دینے کی ترغیب دیتے تھے اور صحابہ سے سفید رنگ کےعمامےاستعمال کرنا ثابت ہے۔اس لئے عمامے میں بھی سیاہ اور سفید رنگ کا استعمال پسندیدہ ہے اگرچہ باقی رنگوں کا استعمال بھی جائز ہے اور اس سے سنت عمامہ ادا ہوجاتی ہے البتہ آج کل سبز رنگ بعض علاقوں میں اہلِ بدعت کا شعار بن چکا ہے اور جو چیز جہاں اہلِ بدعت کا شعار ہو وہاں اس سے اجتناب کرنا چاہئےلہذا ایسی جگہ جہاں اہل بدعت سے مشابہت ہو رہی ہووہاں کسی اور رنگ کا عمامہ استعمال کرلیا جائے۔(ماخذہ التبویب773/2)
نيل الأوطار (2 / 127):
عن أبي عبيد من أن المقعطة هي التي لا ذؤابة لها. وقد استدل على جواز ترك الذؤابة ابن القيم في الهدي بحديث جابر بن سليم عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ:
إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «دخل مكة وعليه عمامة سوداء» بدون ذكر الذؤابة. قال: فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه، وقد يقال: إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه فلبس في كل موطن ما يناسبه اهـ وروى أبو داود من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: «عممني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فسدلها بين يدي ومن خلفي» . وروى الطبراني عن عائشة قالت: «عمم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عبد الرحمن بن عوف وأرخى له أربع أصابع» وفي إسناده المقدام بن داود وهو ضعيف. وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – عمم عبد الرحمن بن عوف فأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها ثم قال: هكذا فاعتم فإنه أعرب وأحسن» قال السيوطي: وإسناده حسن.
المعجم الأوسط (5 / 381):
عن شهر بن حوشب، عن عائشة، قالت: «رأيت جبريل عليه السلام عليه عمامة حمراء، يرخيها بين كتفيه»
تحفة الأحوذي (5 / 336):
(باب في سدل العمامة بين الكتفين)۔۔۔ وحديث عبد الله بن ياسر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى خيبر فعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه أو قال على كتفه اليسرى أخرجه الطبراني وحسنه السيوطي وحديث جابر قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه أخرجه بن عدي وقال لا أعلم يرويه عن أبي الزبير غير
واللہ اعلم بالصواب
نقلہ محمد مصروف مظاہری
الجواب حامدا ومصلیا
عمامہ کسی بھی رنگ کا ہو اس سے سنت ادا ہوجاتی ہے ۔اسی وجہ سے صحابہ سے مختلف رنگ کے عمامے استعمال کرنا ثابت ہے ،جن مین سیاہ ،سفید،پیلا،سبزاور سرخ رنگ شامل ہیں،البتہ رسول اللہ ﷺ سے صراحت کے ساتھ سیاہ رنگ کے عمامے کی روایات ملتی ہیں اور کسی رنگ کے بارے میں ہمیں تلاش بسیار کے باوجود کوئی روایت نہیں ملی ۔ہاں سفید رنگ آپ ﷺ لباس میں پسند فرماتے تھے اور سفید رنگ کے کپڑے میں کفن دینے کی ترغیب دیتے تھے اور صحابہ سے سفید رنگ کےعمامےاستعمال کرنا ثابت ہے۔اس لئے عمامے میں بھی سیاہ اور سفید رنگ کا استعمال پسندیدہ ہے اگرچہ باقی رنگوں کا استعمال بھی جائز ہے اور اس سے سنت عمامہ ادا ہوجاتی ہے البتہ آج کل سبز رنگ بعض علاقوں میں اہلِ بدعت کا شعار بن چکا ہے اور جو چیز جہاں اہلِ بدعت کا شعار ہو وہاں اس سے اجتناب کرنا چاہئےلہذا ایسی جگہ جہاں اہل بدعت سے مشابہت ہو رہی ہووہاں کسی اور رنگ کا عمامہ استعمال کرلیا جائے۔(ماخذہ التبویب773/2)
نيل الأوطار (2 / 127):
عن أبي عبيد من أن المقعطة هي التي لا ذؤابة لها. وقد استدل على جواز ترك الذؤابة ابن القيم في الهدي بحديث جابر بن سليم عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ:
إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «دخل مكة وعليه عمامة سوداء» بدون ذكر الذؤابة. قال: فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه، وقد يقال: إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه فلبس في كل موطن ما يناسبه اهـ وروى أبو داود من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: «عممني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فسدلها بين يدي ومن خلفي» . وروى الطبراني عن عائشة قالت: «عمم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عبد الرحمن بن عوف وأرخى له أربع أصابع» وفي إسناده المقدام بن داود وهو ضعيف. وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – عمم عبد الرحمن بن عوف فأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها ثم قال: هكذا فاعتم فإنه أعرب وأحسن» قال السيوطي: وإسناده حسن.
المعجم الأوسط (5 / 381):
عن شهر بن حوشب، عن عائشة، قالت: «رأيت جبريل عليه السلام عليه عمامة حمراء، يرخيها بين كتفيه»
تحفة الأحوذي (5 / 336):
(باب في سدل العمامة بين الكتفين)۔۔۔ وحديث عبد الله بن ياسر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى خيبر فعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه أو قال على كتفه اليسرى أخرجه الطبراني وحسنه السيوطي وحديث جابر قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه أخرجه بن عدي وقال لا أعلم يرويه عن أبي الزبير غير
واللہ اعلم بالصواب
نقلہ محمد مصروف مظاہری
عمامہ باندھنے کا طریقہ :
حضرت ابوعبد السلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر سے دریافت کیا : نبی کریمﷺکِس طرح عمامہ باندھا کرتے تھے؟ اُنہوں نے فرمایا :آپﷺعمامہ (کے پیچ)کو اپنے سر پر گھمایا کرتے تھےاور پیچھے لاکر دبادیا کرتے تھے، اور عمامہ کا ایک شملہ اپنے دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑدیا کرتے تھے ۔أَبُو عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتِمُ قَالَ:كَانَ يُدِيرُ الْعِمَامَةَ عَلَى رَأْسِهِ وَيَغْرِزُهَا مِنْ وَرَائِهِ وَيُرْسِلُ لَهَا ذُؤَابَةً بَيْنَ كَتِفَيْهِ۔(شعب الایمان :5838)
عمامہ کا شملہ باندھنا :
عمامہ کا شملہ چھوڑنا چاہیئے ، اگر چہ بغیر شملہ کے عمامہ بھی ثابت اور جائز ہے ۔(جمع الوسائل :1/168) لیکن اِس دور میں شملہ کے بغیر پگڑی باندھنا ”سکھوں“ کی علامت بن گیا ہے ، لہٰذا اُن کی مشابہت سے اجتناب ہی کرنا چاہیئے ۔
شَملے کتنے ہونے چاہیئے :
روایات میں ایک شملہ کا بھی ذکر ملتا ہے اور دو کا بھی ثابت ہے : ﴿ایک کا ثبوت﴾حضرت عمرو بن حریث فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو منبر پر تشریف فرما دیکھا اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا جس کے دونوں کناروں کو آپ نے اپنے دونوں کندھوں پر لٹکایا ہوا تھا۔عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ۔(ابوداؤد:4077)
﴿دو کا ثبوت﴾ حضرت عمرو بن حریث فرماتے ہیں کہ وہ منظر میرے سامنے ہے کہ نبی کریمﷺمنبر پر تشریف فرما ہیں اور آپﷺنے سیاہ عمامہ زیب تَن فرمایا ہو ا ہے اور اس کے دونوں شملے آپنے اپنے کندھوں کے درمیان لٹکائے ہوئے ہیں ۔جَعْفَرَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ۔(مسلم:1359)
شملہ کہاں رکھا جائے :
سامنے کی جانب ، پیچھے کی جانب ، دائیں طرف کسی بھی طرف شملہ رکھا جاسکتا ہے ۔(جمع الوسائل :1/168) لیکن اکثر روایات میں چونکہ دونو ں کندھوں کے درمیان پیچھے کا تذکرہ ملتا ہے ، نیز عَمرو بن حُریث کی روایت اس سلسلے میں زیادہ صحیح ہے اِس لئے کندھوں کے درمیان پیچھے لٹکانا نسبتاً افضل ہے ۔(کشف الباری ، کتاب اللباس:170)
شملہ کو کہاں رکھا جائے ، اِس بارے میں روایات ملاحظہ فرمائیں :
﴿پیچھے لٹکانا﴾ حضرت عبادہ نبی کریمﷺکا یہ اِرشاد نقل فرماتے ہیں :عماموں کو اپنے اوپر لازم کرلو، کیونکہ یہ فرشتوں کی نشانی ہے اوراُس کے شملے کو پنی پیٹھ کی جانب لٹکایا کرو۔عَلَيْكُمْ بِالْعَمَائِمِ فَإِنَّهَا سِيمَاءُ الْمَلَائِكَةِ وَأَرْخُوا لَهَا خَلْفَ ظُهُورِكُمْ۔(شعب الایمان :5851)
حضرت عبد اللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب عمامہ باندھتے تو عمامے کے شملے کو دونوں کندھوں کے درمیان لٹکایا کرتے تھے۔حضرت نافع فرماتے ہیں : میں نے حضرت ابن عمر کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا اور حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم اور سالم کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْدِلُ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَرَأَيْتُ القَاسِمَ، وَسَالِمًا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ۔(ترمذی:1736)
(سامنے لٹکانا) حضرت ھشام فرماتے ہیں : میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیکھا کہ اُنہوں نے عمامہ باندھا ہوا تھا اور عمامہ کے دونوں شملے اپنے سامنے کی جانب لٹکائے ہوئے تھے۔عَنْ هِشَامٍ، قَالَ:رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ مُعْتَمًّا قَدْ أَرْخَى طَرَفَيِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ۔(ابن ابی شیبہ :24977)
(ایک شملہ سامنے اور دوسرا پیچھے) حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ نبی کریمﷺنے میرا عمامہ باندھا اور اُس کاشملہ میرے سامنے اور پیچھے کی جانب چھوڑ دیا ۔عَمَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي۔(شعب الایمان :5839)عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عَلِيًّا قَدْ اعْتَمَّ بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ، قَدْ أَرْخَاهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ۔(ابن ابی شیبہ :24959)
(دائیں جانب کانوں کے پاس) حضرت ابوامامہ فرماتے ہیں :نبی کریمﷺجب کسی کو کہیں کا والی بناتے تو اُس کے سر پر عمامہ باندھتے اور اُس کا شملہ دائیں جانب کانوں کےپاس چھوڑ دیتے ۔عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُوَلِّي وَالِيًا حَتَّى يُعَمِّمَهُ، وَيُرْخِيَ لَهَا عَذَبَةً مِنْ جَانِبِ الْأَيْمَنِ نَحْوَ الْأُذُنِ»۔(طبرانی کبیر:7641)
شملہ کی مقدار کتنی ہو
حضرت ابوعبد السلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر سے دریافت کیا : نبی کریمﷺکِس طرح عمامہ باندھا کرتے تھے؟ اُنہوں نے فرمایا :آپﷺعمامہ (کے پیچ)کو اپنے سر پر گھمایا کرتے تھےاور پیچھے لاکر دبادیا کرتے تھے، اور عمامہ کا ایک شملہ اپنے دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑدیا کرتے تھے ۔أَبُو عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتِمُ قَالَ:كَانَ يُدِيرُ الْعِمَامَةَ عَلَى رَأْسِهِ وَيَغْرِزُهَا مِنْ وَرَائِهِ وَيُرْسِلُ لَهَا ذُؤَابَةً بَيْنَ كَتِفَيْهِ۔(شعب الایمان :5838)
عمامہ کا شملہ باندھنا :
عمامہ کا شملہ چھوڑنا چاہیئے ، اگر چہ بغیر شملہ کے عمامہ بھی ثابت اور جائز ہے ۔(جمع الوسائل :1/168) لیکن اِس دور میں شملہ کے بغیر پگڑی باندھنا ”سکھوں“ کی علامت بن گیا ہے ، لہٰذا اُن کی مشابہت سے اجتناب ہی کرنا چاہیئے ۔
شَملے کتنے ہونے چاہیئے :
روایات میں ایک شملہ کا بھی ذکر ملتا ہے اور دو کا بھی ثابت ہے : ﴿ایک کا ثبوت﴾حضرت عمرو بن حریث فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو منبر پر تشریف فرما دیکھا اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا جس کے دونوں کناروں کو آپ نے اپنے دونوں کندھوں پر لٹکایا ہوا تھا۔عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ۔(ابوداؤد:4077)
﴿دو کا ثبوت﴾ حضرت عمرو بن حریث فرماتے ہیں کہ وہ منظر میرے سامنے ہے کہ نبی کریمﷺمنبر پر تشریف فرما ہیں اور آپﷺنے سیاہ عمامہ زیب تَن فرمایا ہو ا ہے اور اس کے دونوں شملے آپنے اپنے کندھوں کے درمیان لٹکائے ہوئے ہیں ۔جَعْفَرَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ۔(مسلم:1359)
شملہ کہاں رکھا جائے :
سامنے کی جانب ، پیچھے کی جانب ، دائیں طرف کسی بھی طرف شملہ رکھا جاسکتا ہے ۔(جمع الوسائل :1/168) لیکن اکثر روایات میں چونکہ دونو ں کندھوں کے درمیان پیچھے کا تذکرہ ملتا ہے ، نیز عَمرو بن حُریث کی روایت اس سلسلے میں زیادہ صحیح ہے اِس لئے کندھوں کے درمیان پیچھے لٹکانا نسبتاً افضل ہے ۔(کشف الباری ، کتاب اللباس:170)
شملہ کو کہاں رکھا جائے ، اِس بارے میں روایات ملاحظہ فرمائیں :
﴿پیچھے لٹکانا﴾ حضرت عبادہ نبی کریمﷺکا یہ اِرشاد نقل فرماتے ہیں :عماموں کو اپنے اوپر لازم کرلو، کیونکہ یہ فرشتوں کی نشانی ہے اوراُس کے شملے کو پنی پیٹھ کی جانب لٹکایا کرو۔عَلَيْكُمْ بِالْعَمَائِمِ فَإِنَّهَا سِيمَاءُ الْمَلَائِكَةِ وَأَرْخُوا لَهَا خَلْفَ ظُهُورِكُمْ۔(شعب الایمان :5851)
حضرت عبد اللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب عمامہ باندھتے تو عمامے کے شملے کو دونوں کندھوں کے درمیان لٹکایا کرتے تھے۔حضرت نافع فرماتے ہیں : میں نے حضرت ابن عمر کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا اور حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم اور سالم کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْدِلُ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَرَأَيْتُ القَاسِمَ، وَسَالِمًا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ۔(ترمذی:1736)
(سامنے لٹکانا) حضرت ھشام فرماتے ہیں : میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیکھا کہ اُنہوں نے عمامہ باندھا ہوا تھا اور عمامہ کے دونوں شملے اپنے سامنے کی جانب لٹکائے ہوئے تھے۔عَنْ هِشَامٍ، قَالَ:رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ مُعْتَمًّا قَدْ أَرْخَى طَرَفَيِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ۔(ابن ابی شیبہ :24977)
(ایک شملہ سامنے اور دوسرا پیچھے) حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ نبی کریمﷺنے میرا عمامہ باندھا اور اُس کاشملہ میرے سامنے اور پیچھے کی جانب چھوڑ دیا ۔عَمَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي۔(شعب الایمان :5839)عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عَلِيًّا قَدْ اعْتَمَّ بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ، قَدْ أَرْخَاهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ۔(ابن ابی شیبہ :24959)
(دائیں جانب کانوں کے پاس) حضرت ابوامامہ فرماتے ہیں :نبی کریمﷺجب کسی کو کہیں کا والی بناتے تو اُس کے سر پر عمامہ باندھتے اور اُس کا شملہ دائیں جانب کانوں کےپاس چھوڑ دیتے ۔عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُوَلِّي وَالِيًا حَتَّى يُعَمِّمَهُ، وَيُرْخِيَ لَهَا عَذَبَةً مِنْ جَانِبِ الْأَيْمَنِ نَحْوَ الْأُذُنِ»۔(طبرانی کبیر:7641)
شملہ کی مقدار کتنی ہو
نی چاہیئے :
اِس بارے میں مختلف اقوال احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں :
(1)ایک ذراع ۔ (2) ایک بالشت ۔ (3)چار انگلیوں کے بقدر۔(عون المعبود :11/89)
ان میں سے کسی پر بھی عمل کرسکتے ہیں ، البتہ "نصفِ ظَہر" کم کم ہونا چاہیئے ، اِس سے زیادہ لمبا شملہ ”اِسبال فی العمامہ “ کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے درست نہیں ۔ اِسبال فی العمامہ کی تفصیل آگے آرہی ہے ۔
(ایک ذراع)- حضرت سلمہ بن وردان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کو سیاہ عمامہ پہنے ہوئے دیکھا جو اُنہوں نے بغیر ٹوپی کے باندھا ہوتھا اور اُس کا شملہ پیچھے کی جانب ایک ذراع کے بقدر چھوڑ رکھا تھا۔سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ، قَالَ:رَأَيْتُ عَلَى أَنَسٍ عِمَامَةً سَوْدَاءَ عَلَى غَيْرِ قَلَنْسُوَةٍ، وَقَدْ أَرْخَاهَا مِنْ خَلْفِهِ نَحْوًا مِنْ ذِرَاعٍ۔(ابن ابی شیبہ :24955)عُمَرُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: " رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ مُعْتَمًّا قَدْ أَرْخَى عِمَامَتَهُ مِنْ خَلْفِهِ ذِرَاعًا۔(شعب الایمان:5843)
(ایک بالشت)- اسماعیل ابن عبد الملک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیرکو دیکھا ہے وہ عمامہ باندھا کرتے تھے اور اُس کا شملہ پیچھے کی جانب ایک بالشت چھوڑا کرتے تھے۔وَكَانَ يَعْتَمُّ وَيُرْخِي لَهَا طرفا شبرا من ورائه۔(طبقات لابن سعد :6/272)عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَعْتَمُّ بِعِمَامَةِ حَرْقَانِيَّةٍ وَيُرْخِيهَا شبرا وأقل من شبر۔(طبقات لابن سعد :4/200)عَنْ رِشْدِينَ قال: رأيت محمد ابن الْحَنَفِيَّةِ يَعْتَمُّ بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ حَرْقَانِيَّةٍ وَيُرْخِيهَا شِبْرًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ شِبْرٍ۔(طبقات لابن سعد :5/85)
﴿چار انگلیوں کے بقدر)- حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں :عمامہ میں افضل یہ ہے کہ چارانگلیوں کے بقدر یا اس کے قریب قریب شملہ چھوڑا جائے ۔وَأَفْضَلُ عِمَامَتِهِ، مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ۔(شعب الایمان:5840) حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کالے رنگ کا ایک کھردرے کپڑے کا عمامہ پہنا ہوا تھا ،آپﷺنے اُنہیں اپنے قریب بلایا اور اُن کاعمامہ کھولا اور پھر اُن کے سر پر سفید عِمامہ باندھا، اور اُس کا شَملہ پیچھے کی جانب چار انگلیوں یا اس کے قریب قریب کی مقدار کے برابر چھوڑ دیا اور فرمایا :،پھر آپﷺنے فرمایا : اے ابن عوف! اِس طرح سے عمامہ باندھا کرو ، اِس لئے کہ یہ بہت ہی واضح (عربی ) اور خوبصورت ہے۔وَأَصْبَحَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَدِ اعْتَمَّ بِعِمَامَةٍ مَنْ كَرَابِيسَ سَوْدَاءَ، فَأَدْنَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَقَضَهُ وَعَمَّمَهُ بِعِمَامَةٍ بَيْضَاءَ، وَأَرْسَلَ مِنْ خَلْفِهِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَقَالَ: «هَكَذَا يَا ابْنَ عَوْفٍ اعْتَمَّ فَإِنَّهُ أَعْرَبُ وَأَحْسَنُ»۔(مستدرکِ حاکم:4/582)
اِسبال فی العمامہ :
حضرت عبد اللہ بن عمر نبی کریمﷺکا یہ اِرشاد نقل فرماتے ہیں : اِسبال(یعنی کپڑوں کا لٹکانا) قمیص ، اِزار ، اور عمامہ سب میں ہوتا ہے۔عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ، وَالْقَمِيصِ، وَالْعِمَامَةِ۔(ابوداؤد :4094)(شعب الایمان :5723)یعنی جس طرح شلوار میں اِسبال ہوتا ہے کہ اُسے ٹخنوں سے نیچے رکھنا درست نہیں اِسی طرح عمامہ میں بھی اِسبال ہوتا ہے اور عمامہ میں اِسبال یہ ہے کہ ”نصفِ ظَہر“ یعنی آدھی کمر سے نیچے رکھا جائے ، چنانچہ عمامہ کے شملہ کا اِس قدر طویل ہونا کہ نصفِ ظَہر سے تجاوز کرجائے ، یہ اِسبال کے تحت داخل ہونےکی وجہ سے ممنوع ہے۔(اشعۃ اللمعات ، بحوالہ کشف الباری، کتاب اللباس :170، 171)
عمامہ کو ٹوپی کے اوپر پہننا چاہیئے:-
حضرت ابو جعفر بن محمد بن رکانہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت رکانہ نے نبی کریمﷺکے ساتھ کُشتی کی تو آپ نے انہیں پچھاڑ دیا۔حضرت رکانہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان ٹوپیوں پر عمامہ باندھنے کا فرق ہے(یعنی مُشرکین بغیر ٹوپی کے اور مسلمان ٹوپی پہن کر عمامہ باندھتے ہیں)۔عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رُكَانَةُ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:إِنَّ فَرْقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ المُشْرِكِينَ العَمَائِمُ عَلَى القَلَانِسِ۔(ترمذی:1784)
عمامہ کا رنگ :
نبی کریمﷺسے مختلف رنگوں کا عمامہ پہننا ثابت ہے:
(1)سیاہ عمامہ ۔ (2)سفیدعمامہ۔ (3)زرد عمامہ ۔ (4)سُرخ عمامہ ۔
کالا عمامہ :
حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺفتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرّمہ میں داخل ہوئے تو آپ ﷺکے سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا۔عَنْ جَابِرٍ قَالَ
اِس بارے میں مختلف اقوال احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں :
(1)ایک ذراع ۔ (2) ایک بالشت ۔ (3)چار انگلیوں کے بقدر۔(عون المعبود :11/89)
ان میں سے کسی پر بھی عمل کرسکتے ہیں ، البتہ "نصفِ ظَہر" کم کم ہونا چاہیئے ، اِس سے زیادہ لمبا شملہ ”اِسبال فی العمامہ “ کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے درست نہیں ۔ اِسبال فی العمامہ کی تفصیل آگے آرہی ہے ۔
(ایک ذراع)- حضرت سلمہ بن وردان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کو سیاہ عمامہ پہنے ہوئے دیکھا جو اُنہوں نے بغیر ٹوپی کے باندھا ہوتھا اور اُس کا شملہ پیچھے کی جانب ایک ذراع کے بقدر چھوڑ رکھا تھا۔سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ، قَالَ:رَأَيْتُ عَلَى أَنَسٍ عِمَامَةً سَوْدَاءَ عَلَى غَيْرِ قَلَنْسُوَةٍ، وَقَدْ أَرْخَاهَا مِنْ خَلْفِهِ نَحْوًا مِنْ ذِرَاعٍ۔(ابن ابی شیبہ :24955)عُمَرُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: " رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ مُعْتَمًّا قَدْ أَرْخَى عِمَامَتَهُ مِنْ خَلْفِهِ ذِرَاعًا۔(شعب الایمان:5843)
(ایک بالشت)- اسماعیل ابن عبد الملک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیرکو دیکھا ہے وہ عمامہ باندھا کرتے تھے اور اُس کا شملہ پیچھے کی جانب ایک بالشت چھوڑا کرتے تھے۔وَكَانَ يَعْتَمُّ وَيُرْخِي لَهَا طرفا شبرا من ورائه۔(طبقات لابن سعد :6/272)عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَعْتَمُّ بِعِمَامَةِ حَرْقَانِيَّةٍ وَيُرْخِيهَا شبرا وأقل من شبر۔(طبقات لابن سعد :4/200)عَنْ رِشْدِينَ قال: رأيت محمد ابن الْحَنَفِيَّةِ يَعْتَمُّ بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ حَرْقَانِيَّةٍ وَيُرْخِيهَا شِبْرًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ شِبْرٍ۔(طبقات لابن سعد :5/85)
﴿چار انگلیوں کے بقدر)- حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں :عمامہ میں افضل یہ ہے کہ چارانگلیوں کے بقدر یا اس کے قریب قریب شملہ چھوڑا جائے ۔وَأَفْضَلُ عِمَامَتِهِ، مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ۔(شعب الایمان:5840) حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کالے رنگ کا ایک کھردرے کپڑے کا عمامہ پہنا ہوا تھا ،آپﷺنے اُنہیں اپنے قریب بلایا اور اُن کاعمامہ کھولا اور پھر اُن کے سر پر سفید عِمامہ باندھا، اور اُس کا شَملہ پیچھے کی جانب چار انگلیوں یا اس کے قریب قریب کی مقدار کے برابر چھوڑ دیا اور فرمایا :،پھر آپﷺنے فرمایا : اے ابن عوف! اِس طرح سے عمامہ باندھا کرو ، اِس لئے کہ یہ بہت ہی واضح (عربی ) اور خوبصورت ہے۔وَأَصْبَحَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَدِ اعْتَمَّ بِعِمَامَةٍ مَنْ كَرَابِيسَ سَوْدَاءَ، فَأَدْنَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَقَضَهُ وَعَمَّمَهُ بِعِمَامَةٍ بَيْضَاءَ، وَأَرْسَلَ مِنْ خَلْفِهِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَقَالَ: «هَكَذَا يَا ابْنَ عَوْفٍ اعْتَمَّ فَإِنَّهُ أَعْرَبُ وَأَحْسَنُ»۔(مستدرکِ حاکم:4/582)
اِسبال فی العمامہ :
حضرت عبد اللہ بن عمر نبی کریمﷺکا یہ اِرشاد نقل فرماتے ہیں : اِسبال(یعنی کپڑوں کا لٹکانا) قمیص ، اِزار ، اور عمامہ سب میں ہوتا ہے۔عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ، وَالْقَمِيصِ، وَالْعِمَامَةِ۔(ابوداؤد :4094)(شعب الایمان :5723)یعنی جس طرح شلوار میں اِسبال ہوتا ہے کہ اُسے ٹخنوں سے نیچے رکھنا درست نہیں اِسی طرح عمامہ میں بھی اِسبال ہوتا ہے اور عمامہ میں اِسبال یہ ہے کہ ”نصفِ ظَہر“ یعنی آدھی کمر سے نیچے رکھا جائے ، چنانچہ عمامہ کے شملہ کا اِس قدر طویل ہونا کہ نصفِ ظَہر سے تجاوز کرجائے ، یہ اِسبال کے تحت داخل ہونےکی وجہ سے ممنوع ہے۔(اشعۃ اللمعات ، بحوالہ کشف الباری، کتاب اللباس :170، 171)
عمامہ کو ٹوپی کے اوپر پہننا چاہیئے:-
حضرت ابو جعفر بن محمد بن رکانہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت رکانہ نے نبی کریمﷺکے ساتھ کُشتی کی تو آپ نے انہیں پچھاڑ دیا۔حضرت رکانہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان ٹوپیوں پر عمامہ باندھنے کا فرق ہے(یعنی مُشرکین بغیر ٹوپی کے اور مسلمان ٹوپی پہن کر عمامہ باندھتے ہیں)۔عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رُكَانَةُ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:إِنَّ فَرْقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ المُشْرِكِينَ العَمَائِمُ عَلَى القَلَانِسِ۔(ترمذی:1784)
عمامہ کا رنگ :
نبی کریمﷺسے مختلف رنگوں کا عمامہ پہننا ثابت ہے:
(1)سیاہ عمامہ ۔ (2)سفیدعمامہ۔ (3)زرد عمامہ ۔ (4)سُرخ عمامہ ۔
کالا عمامہ :
حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺفتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرّمہ میں داخل ہوئے تو آپ ﷺکے سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا۔عَنْ جَابِرٍ قَالَ
:دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ۔(ترمذی:1735)
حضرت عمرو بن حریث ، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو منبر پر تشریف فرما دیکھا اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا جس کے دونوں کناروں کو آپ نے اپنے دونوں کندھوں پر لٹکایا ہوا تھا۔عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ۔(ابوداؤد:4077)
سفید عمامہ :
حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کالے رنگ کا ایک کھردرے کپڑے کا عمامہ پہنا ہوا تھا ،آپﷺنے اُنہیں اپنے قریب بلایا اور اُن کاعمامہ کھولا اور پھر اُن کے سر پر سفید عِمامہ باندھا، اور اُس کا شَملہ پیچھے کی جانب چار انگلیوں یا اس کے قریب قریب کی مقدار کے برابر چھوڑ دیا اور فرمایا :،پھر آپﷺنے فرمایا : اے ابن عوف! اِس طرح سے عمامہ باندھا کرو ، اِس لئے کہ یہ بہت ہی اچھا اور خوبصورت ہے۔وَأَصْبَحَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَدِ اعْتَمَّ بِعِمَامَةٍ مَنْ كَرَابِيسَ سَوْدَاءَ، فَأَدْنَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَقَضَهُ وَعَمَّمَهُ بِعِمَامَةٍ بَيْضَاءَ، وَأَرْسَلَ مِنْ خَلْفِهِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَقَالَ: «هَكَذَا يَا ابْنَ عَوْفٍ اعْتَمَّ فَإِنَّهُ أَعْرَبُ وَأَحْسَنُ»۔(مستدرکِ حاکم:4/582) الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:رَأَيْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ عِمَامَةً بَيْضَاءَ قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا، وَلَمْ يُرْسِلْهُ۔(ابن ابی شیبہ :24972)إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ:«رَأَيْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عِمَامَةً بَيْضَاءَ»۔(ابن ابی شیبہ :24973)
زرد عمامہ :
حضرت عبد اللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریمﷺ کو دو زعفران میں رنگے ہوئے کپڑوں میں دیکھا ، ایک کپڑاچادر تھی اور دوسرا کپڑا عمامہ تھا۔عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مَصْبُوغَانِ بِالزَّعْفَرَانِ رِدَاءٌ وَعِمَامَةٌ»۔(مستدرکِ حاکم:4/209 ، رقم :7395)
حضرت ابن عمر اپنی داڑھی کو زرد رنگ کرتے تھے، حتی کہ ان کے کپڑے بھی زرد ہوتے تھے تو ان سے کہا گیا کہ آپ زرد رنگ سے کیوں رنگتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہﷺ کو دیکھا کہ آپ زرد رنگ سے رنگا کرتے تھے اور حضور اکرم ﷺ کو اس سے زیادہ کوئی رنگ پسند نہیں تھا اور کبھی آپ ﷺ اس سے اپنے سارے کپڑوں کو بھی رنگا کرتے تھے ،یہاں تک کہ اپنا عمامہ بھی ۔عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَسْلَمَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَصْبُغُ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ حَتَّى تَمْتَلِئَ ثِيَابُهُ مِنَ الصُّفْرَةِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْهَا، وَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ۔(ابوداؤد:406)
حضرت سیدنا ابوہریرہ فرماتے ہیں:- نبی کریمﷺہمارے پاس نکل کر آئے ،آپ نے زرد رنگ کی قمیص ، زرد رنگ کی چادر اور زرد رنگ کا عمامہ زیب تَن فرمایا ہوا تھا۔عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ أَصْفَرُ وَرِدَاءٌ أَصْفَرُ وَعِمَامَةٌ صَفْرَاءُ»۔(تاریخ دمشق لابن عساکر:34/385، رقم:3814)
سُرخ عمامہ :
حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریمﷺکووضو کرتے دیکھا ، آپﷺ نے قِطری(سرخ دھاریوں والا کھردرا ) عِمامہ پہنا ہوا تھا، آپ نے عمامہ کے نیچے سے اپنا ہاتھ داخل فرماکر عمامہ کھولے بغیرسر کے اگلے حصہ کا مسح فرمایا۔رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ۔(ابوداؤد:147)هُوَ ضَرْب مِنَ البُرود فِيهِ حُمْرة، وَلَهَا أعْلام فِيهَا بَعْضُ الْخُشُونَةِ۔(النھایۃ لابن الأثیر:4/80)وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى التَّعَمُّمِ بِالْحُمْرَةِ وَهُوَ اسْتِدْلَالٌ صَحِيحٌ۔(عون المعبود:1/172)
ناقل: احقر شبیر احمد غفر لہ
حضرت عمرو بن حریث ، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو منبر پر تشریف فرما دیکھا اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا جس کے دونوں کناروں کو آپ نے اپنے دونوں کندھوں پر لٹکایا ہوا تھا۔عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ۔(ابوداؤد:4077)
سفید عمامہ :
حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کالے رنگ کا ایک کھردرے کپڑے کا عمامہ پہنا ہوا تھا ،آپﷺنے اُنہیں اپنے قریب بلایا اور اُن کاعمامہ کھولا اور پھر اُن کے سر پر سفید عِمامہ باندھا، اور اُس کا شَملہ پیچھے کی جانب چار انگلیوں یا اس کے قریب قریب کی مقدار کے برابر چھوڑ دیا اور فرمایا :،پھر آپﷺنے فرمایا : اے ابن عوف! اِس طرح سے عمامہ باندھا کرو ، اِس لئے کہ یہ بہت ہی اچھا اور خوبصورت ہے۔وَأَصْبَحَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَدِ اعْتَمَّ بِعِمَامَةٍ مَنْ كَرَابِيسَ سَوْدَاءَ، فَأَدْنَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَقَضَهُ وَعَمَّمَهُ بِعِمَامَةٍ بَيْضَاءَ، وَأَرْسَلَ مِنْ خَلْفِهِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَقَالَ: «هَكَذَا يَا ابْنَ عَوْفٍ اعْتَمَّ فَإِنَّهُ أَعْرَبُ وَأَحْسَنُ»۔(مستدرکِ حاکم:4/582) الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:رَأَيْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ عِمَامَةً بَيْضَاءَ قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا، وَلَمْ يُرْسِلْهُ۔(ابن ابی شیبہ :24972)إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ:«رَأَيْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عِمَامَةً بَيْضَاءَ»۔(ابن ابی شیبہ :24973)
زرد عمامہ :
حضرت عبد اللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریمﷺ کو دو زعفران میں رنگے ہوئے کپڑوں میں دیکھا ، ایک کپڑاچادر تھی اور دوسرا کپڑا عمامہ تھا۔عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مَصْبُوغَانِ بِالزَّعْفَرَانِ رِدَاءٌ وَعِمَامَةٌ»۔(مستدرکِ حاکم:4/209 ، رقم :7395)
حضرت ابن عمر اپنی داڑھی کو زرد رنگ کرتے تھے، حتی کہ ان کے کپڑے بھی زرد ہوتے تھے تو ان سے کہا گیا کہ آپ زرد رنگ سے کیوں رنگتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہﷺ کو دیکھا کہ آپ زرد رنگ سے رنگا کرتے تھے اور حضور اکرم ﷺ کو اس سے زیادہ کوئی رنگ پسند نہیں تھا اور کبھی آپ ﷺ اس سے اپنے سارے کپڑوں کو بھی رنگا کرتے تھے ،یہاں تک کہ اپنا عمامہ بھی ۔عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَسْلَمَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَصْبُغُ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ حَتَّى تَمْتَلِئَ ثِيَابُهُ مِنَ الصُّفْرَةِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْهَا، وَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ۔(ابوداؤد:406)
حضرت سیدنا ابوہریرہ فرماتے ہیں:- نبی کریمﷺہمارے پاس نکل کر آئے ،آپ نے زرد رنگ کی قمیص ، زرد رنگ کی چادر اور زرد رنگ کا عمامہ زیب تَن فرمایا ہوا تھا۔عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ أَصْفَرُ وَرِدَاءٌ أَصْفَرُ وَعِمَامَةٌ صَفْرَاءُ»۔(تاریخ دمشق لابن عساکر:34/385، رقم:3814)
سُرخ عمامہ :
حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریمﷺکووضو کرتے دیکھا ، آپﷺ نے قِطری(سرخ دھاریوں والا کھردرا ) عِمامہ پہنا ہوا تھا، آپ نے عمامہ کے نیچے سے اپنا ہاتھ داخل فرماکر عمامہ کھولے بغیرسر کے اگلے حصہ کا مسح فرمایا۔رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ۔(ابوداؤد:147)هُوَ ضَرْب مِنَ البُرود فِيهِ حُمْرة، وَلَهَا أعْلام فِيهَا بَعْضُ الْخُشُونَةِ۔(النھایۃ لابن الأثیر:4/80)وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى التَّعَمُّمِ بِالْحُمْرَةِ وَهُوَ اسْتِدْلَالٌ صَحِيحٌ۔(عون المعبود:1/172)
ناقل: احقر شبیر احمد غفر لہ
*امام مقتدیوں سے کتنی بلندی پر کھڑا رہ سکتا ہے؟:*
سوال
امام مقتدیوں سے کتنی بلندی پر کھڑا رہے تو وہ مکروہ ہے ؟ بلندی کی کم از کم حد کتنی ؟
الجواب حامداً ومصلیاً
*بلندی کی کم از کم مقدار اور حد کے متعلق فقہا ؒ میں اختلاف ہے اس لئے کہ اس کے متعلق جو احادیث آئی ہیں ان میں مقدار کی تصریح نہیں ہے ، حدیث میں ہے*
آنحضرتﷺنے امام کو مقتدی سے بلند جگہ پر کھڑے رہنے سے ممانعت فرمائی۔روی الحاکم مرفوعاً نھی رسول اﷲ ﷺ ان یقوم الا مام فوقا و یبقی الناس خلفہ الخ
(طحطاوی علی الدر المختار ج۱ ص ۴۳۱مکروھات الصلوۃ)(شامی ج۱ ص ۶۰۴ ایضا)
(عینی شرح ہدایہ ج۱ ص ۸۰۵ ایضا)
اور ابو دائود شڑیف میں روایت ہے کہ حضرت عمار بن یاسر ؓ نے مدائن میں نماز پڑھائی تو مقتدیوں سے بلندی پر کھڑے رہے حضرت حذیفہ ؓ یہ دیکھ کر آگے بڑھے اور ہاتھ پکڑ کر نیچے کھینچ لائے نماز کے بعد فرمایا کیا آپ نے آنحضرتﷺکا یہ ارشاد نہیں سنا کہ
’’ اذا ام الرجل القوم فلا یقم فی مکان ارفع من مقامھم او نحوذلک قال عمار لذلک اتبعتک حین اخذت علی یدی
( ابوداؤد شریف ج ۱ ص ۹۵ باب الامام لقوم مکانا ارفع منھم )
(ترجمہ) جب کوئی شخص کسی جماعت کی امامت کرے تو ایسی جگہ نہ کھڑا ہو جو جماعت کی جگہ سے بلند ہو ۔ حضرت عمار نے فرمایا اسی لئے تو میں نے یہ کیا کہ جب آپ نے میرا ہاتھ پکڑا میں نے آپ کی تعمیل کر دی۔
*ان دونوں روایتوں میں بلندی کی کوئی حد اور مقدار مذکور نہیں ہے ، اس لئے اختلاف ہونا قدرتی ہے لہذا مقدار کے متعلق کئی قول ہیں جن میں دو قول معتبر سمجھے گئے ہیں ۔*
(۱)ایک ذراع یعنی ایک ہاتھ کی مقدار بلندی ممنوع و مکروہ ہے ،اس سے کم مکروہ نہیں ہے ، دلیل یہ ہے کہ نمازی کے لئے سترہ کی بلندی کی مقدار کم از کم ایک ذراع (ہاتھ) مانی گئی ہے اس پر قیاس کر کے جگہ کی بلندی بھی ایک ہاتھ ماننی چاہئے کہ بمقدار سترہ بلندی مکروہ ہے اس سے کم مکروہ نہیں ۔
(۲)اتنی بلندی پر کھڑا ہونا مکروہ ہے کہ نمایاں طور پر امام مقتدیوں سے ممتاز اور الگ معلوم ہوتا ہو دلیل یہ ہے کہ احادیث میں مطلق بلندی ممنوع ہے لہذا جس صورت میں امام مقتدی سے بلندی میں ممتاز اورنمایاں طور پر جدا معلوم ہوتا ہو اتنی بلندی مکروہ اور ممنوع ہونی چاہئے اور جیسے جیسے یہ بلندی بڑھتی جائے گی کراہت میں زیادتی ہوتی جائے گی ۔ صاحب بدائع وغیرہ فقہاء نے اسی قول کی تائید کی ہے اور اسے ظاہر روایت بتلایا ہے ۔(البدائع والصنائع ج ۱ ص ۲۸۱)
*(۱) شیخ ابن ہمام رحمہ اﷲ نے یہی قول اختیار کیا ہے*
(فتح القدیر ج۱ ص ۳۶۰ فصل ویکرہ للمصلی )
اورزادالفقیر میں تحریر فرماتے ہیں ۔وقیامہ علی مکان مرتفع وھو ما یقع بہ التمیز ظاھراً وحدہ (یعنی)
(مکروہ ہے ) اکیلے امام کا اتنی بلندجگہ پر کھڑا رہنا جو ظاہراً ممتاز معلوم ہوا ور صاف طور پر الگ دکھائی دے (ص۵۰)
*’’بحرالرائق‘‘ میں ہے کہ ظاہر روایت اور اطلاق حدیث کے بموجب عمل کرنا بہتر ہے*
فالحاصل ان التصحیح قد اختلف والا ولی العمل بظاہر الروایۃ واطلاق الحدیث
( ص۲۶ج۲)
*علامہ طحطاویؒ اور علامہ شامی ؒ نے بھی دوسرے قول کی تائید اور موافقت فرمائی ہے*
(قولہ وھوالا وجہ )
وھو ظاھر الروایۃ والروایات قد اختلفت فی المقدار الا خذ بظاہر الروایۃ اولیٰ (طحطاوی ج۱ ص ۳۴۱ مکروہات صلاۃ)
(قولہ وقیل الخ ) ھو ظاہر الروایۃ کما فی البدائع الخ (شامی ایضاً ج۱ ص ۶۰۵)
واﷲ اعلم بالصواب۔
محمد مصروف مظاہری
سوال
امام مقتدیوں سے کتنی بلندی پر کھڑا رہے تو وہ مکروہ ہے ؟ بلندی کی کم از کم حد کتنی ؟
الجواب حامداً ومصلیاً
*بلندی کی کم از کم مقدار اور حد کے متعلق فقہا ؒ میں اختلاف ہے اس لئے کہ اس کے متعلق جو احادیث آئی ہیں ان میں مقدار کی تصریح نہیں ہے ، حدیث میں ہے*
آنحضرتﷺنے امام کو مقتدی سے بلند جگہ پر کھڑے رہنے سے ممانعت فرمائی۔روی الحاکم مرفوعاً نھی رسول اﷲ ﷺ ان یقوم الا مام فوقا و یبقی الناس خلفہ الخ
(طحطاوی علی الدر المختار ج۱ ص ۴۳۱مکروھات الصلوۃ)(شامی ج۱ ص ۶۰۴ ایضا)
(عینی شرح ہدایہ ج۱ ص ۸۰۵ ایضا)
اور ابو دائود شڑیف میں روایت ہے کہ حضرت عمار بن یاسر ؓ نے مدائن میں نماز پڑھائی تو مقتدیوں سے بلندی پر کھڑے رہے حضرت حذیفہ ؓ یہ دیکھ کر آگے بڑھے اور ہاتھ پکڑ کر نیچے کھینچ لائے نماز کے بعد فرمایا کیا آپ نے آنحضرتﷺکا یہ ارشاد نہیں سنا کہ
’’ اذا ام الرجل القوم فلا یقم فی مکان ارفع من مقامھم او نحوذلک قال عمار لذلک اتبعتک حین اخذت علی یدی
( ابوداؤد شریف ج ۱ ص ۹۵ باب الامام لقوم مکانا ارفع منھم )
(ترجمہ) جب کوئی شخص کسی جماعت کی امامت کرے تو ایسی جگہ نہ کھڑا ہو جو جماعت کی جگہ سے بلند ہو ۔ حضرت عمار نے فرمایا اسی لئے تو میں نے یہ کیا کہ جب آپ نے میرا ہاتھ پکڑا میں نے آپ کی تعمیل کر دی۔
*ان دونوں روایتوں میں بلندی کی کوئی حد اور مقدار مذکور نہیں ہے ، اس لئے اختلاف ہونا قدرتی ہے لہذا مقدار کے متعلق کئی قول ہیں جن میں دو قول معتبر سمجھے گئے ہیں ۔*
(۱)ایک ذراع یعنی ایک ہاتھ کی مقدار بلندی ممنوع و مکروہ ہے ،اس سے کم مکروہ نہیں ہے ، دلیل یہ ہے کہ نمازی کے لئے سترہ کی بلندی کی مقدار کم از کم ایک ذراع (ہاتھ) مانی گئی ہے اس پر قیاس کر کے جگہ کی بلندی بھی ایک ہاتھ ماننی چاہئے کہ بمقدار سترہ بلندی مکروہ ہے اس سے کم مکروہ نہیں ۔
(۲)اتنی بلندی پر کھڑا ہونا مکروہ ہے کہ نمایاں طور پر امام مقتدیوں سے ممتاز اور الگ معلوم ہوتا ہو دلیل یہ ہے کہ احادیث میں مطلق بلندی ممنوع ہے لہذا جس صورت میں امام مقتدی سے بلندی میں ممتاز اورنمایاں طور پر جدا معلوم ہوتا ہو اتنی بلندی مکروہ اور ممنوع ہونی چاہئے اور جیسے جیسے یہ بلندی بڑھتی جائے گی کراہت میں زیادتی ہوتی جائے گی ۔ صاحب بدائع وغیرہ فقہاء نے اسی قول کی تائید کی ہے اور اسے ظاہر روایت بتلایا ہے ۔(البدائع والصنائع ج ۱ ص ۲۸۱)
*(۱) شیخ ابن ہمام رحمہ اﷲ نے یہی قول اختیار کیا ہے*
(فتح القدیر ج۱ ص ۳۶۰ فصل ویکرہ للمصلی )
اورزادالفقیر میں تحریر فرماتے ہیں ۔وقیامہ علی مکان مرتفع وھو ما یقع بہ التمیز ظاھراً وحدہ (یعنی)
(مکروہ ہے ) اکیلے امام کا اتنی بلندجگہ پر کھڑا رہنا جو ظاہراً ممتاز معلوم ہوا ور صاف طور پر الگ دکھائی دے (ص۵۰)
*’’بحرالرائق‘‘ میں ہے کہ ظاہر روایت اور اطلاق حدیث کے بموجب عمل کرنا بہتر ہے*
فالحاصل ان التصحیح قد اختلف والا ولی العمل بظاہر الروایۃ واطلاق الحدیث
( ص۲۶ج۲)
*علامہ طحطاویؒ اور علامہ شامی ؒ نے بھی دوسرے قول کی تائید اور موافقت فرمائی ہے*
(قولہ وھوالا وجہ )
وھو ظاھر الروایۃ والروایات قد اختلفت فی المقدار الا خذ بظاہر الروایۃ اولیٰ (طحطاوی ج۱ ص ۳۴۱ مکروہات صلاۃ)
(قولہ وقیل الخ ) ھو ظاہر الروایۃ کما فی البدائع الخ (شامی ایضاً ج۱ ص ۶۰۵)
واﷲ اعلم بالصواب۔
محمد مصروف مظاہری
*👁کرپٹو کرنسی، تعارف اور حقیقت👁*
*(بٹ کوائن (Bit Coin) اور ون کوائن (Onecoin) پر ایک نظر)*
*از قلم: محمد زبیر الندوی*
*مركز البحث والإفتاء ممبئی انڈیا*
رابطہ 9029189288
جس طرح انسانی زندگی میں مختلف تبدیلیاں اور نیرنگیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں؛ اسی طرح کائنات کا نظام اور چیزیں بھی ان تبدیلیوں سے دو چار اور متاثر ہوتی رہتی ہیں، اسی لئے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی کسی شی کو دوام نہیں، مثل مشہور ہے "ہر کمالے را زوالے" ہر کمال کو زوال سے ضرور دوچار ہونا پڑتا ہے۔
آجکل ہمارے ہاتھوں میں جو کرنسی کی شکل میں پیسے یا روپئے موجود ہیں؛ ان کی کہانی بھی بڑی عجیب اور ان پر آنے والی تبدیلیاں بڑی حیرت انگیز ہیں، نوع انسانی کے ابتدائی دور اور بعد کے ادوار میں ایک طویل عرصہ ایسا گزرا ہے جب سونا چاندی اور روپئے پیسے کا بطور تبادلہ کوئی خیال تک نہ تھا، اس دور میں اشیاء کا تبادلہ اشیاء سے ہوتا تھا، چاول دیکر گیہوں لے لینا اور آٹا دے کر دودھ لے لینا ہی چیزوں کی خرید و فروخت کی مانی جانی شکل تھی، پھر ایک دور آیا کہ یہی تبادلہ سونے چاندی جیسی بیش قیمت دھاتوں سے ہونے لگا، انہیں کے ذریعے چیزیں خریدی اور فروخت کی جانے لگیں؛ لیکن بہت مدت نہیں گزری کہ خرید و فروخت کی دراز دستی نے سونے چاندی کے خول سے نکل کر ان سے بنے سکوں اور مختلف دھاتوں سے بنے پیسوں کی شکل اختیار کر لی۔
پھر ان کے بعد ایک ایسا بھی دور آیا جب لوگ سونے چاندی اور ان کے سکوں کو صرافوں کے پاس رکھ دیتے اور ان سے اس کی رسیدیں حاصل کرلیتے اور بوقت ضرورت رسید دکھا کر وہ سکے واپس لے لئے جاتے اور اگر کسی کو دینے کی ضرورت پیش آتی تو بعض فرزانے ایسا بھی کرتے کہ وہی رسید کسی اور کو دے دیتے اور وہ رسید دکھا کر صراف سے سونا لے لیتا، اور کبھی کبھی انہیں رسیدوں سے لوگ اشیاء کی خرید و فروخت کا معاملہ بھی کر لیتے، آہستہ آہستہ یہ سلسلہ عام اور دراز سے دراز تر ہوتا گیا، یہی وہ دور ہے جس کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ یہ نوٹوں کے آغاز کا ابتدائی زمانہ تھا اور جس کی اعلی ترین شکل اب ہمارے زمانے میں اس قدر عام ہے کہ اس کے خلاف سوچنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔
کرنسی نوٹ کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جوں جوں اس میں ترقی ہوتی گئی یہ اپنی اصلیت یعنی "ثمن حقیقی" سے دور سے دور تر ہوتی چلی گئی، کسی زمانے میں ان کرنسیوں کے پیچھے سو فیصد سونا ہوا کرتا تھا، پھر ایک زمانہ آیا کہ انہیں ڈالر سے جوڑ دیا گیا اور ڈالر کے پیچھے سونا تسلیم کر لیا گیا تھا، گویا بالواسطہ ان کے پیچھے سونا موجود تھا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کرنسیوں نے ڈالر سے بھی اپنا دامن چھڑا لیا اور اب ہم جس کرنسی کے دیوانے ہیں اور جس کی دستیابی کے لئے مر مٹ رہے ہیں اس کا سونے چاندی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے اور سوائے اس کی کہ اسے قانونی طور پر خرید و فروخت کا ایک ذریعہ تسلیم کر لیا گیا ہے اس کی حیثیت ایک کاغذ سے زیادہ نہیں۔
مگر جیسا کہ اوپر ذکر ہوا "ہر کمالے را زوالے" کچھ انسانوں کو شاید یہ سکے اور کاغذی نوٹ بھی بوجھ معلوم ہو رہے تھے یا یوں کہہ لیجیے کہ کرنسی نے ایک نئی انقلابی کروٹ لی اور اب ایک ایسی کرنسی وجود میں آچکی ہے؛ جسے جیب میں رکھنے اور چور اچکوں سے محفوظ رکھنے کی فکر دامن گیر نہ ہو گی، اس کرنسی سے انسان اپنی تمام تر ضروریات کی تکمیل بھی کر سکے گا اور پیسوں، سکوں کے بوجھت سے بھی آزاد ہوگا، ذیل میں اسی کرنسی سے متعلق چند اہم معلومات فراہم کی جاتی ہیں امید کہ اس تحریر سے اس نومولود کرنسی کو سمجھنا آسان ہوگا۔
اس وقت تمام دنیا میں آن لائن کارو بار کا جو طوفان برپا ہوا ہے اور معیشت و تجارت میں جو زبردست ہلچل اور گہما گہمی پیدا ہوئی ہے شاید ماضی کے کسی زمانے میں پیدا نہیں ہوئی ہوگی، اسی ہلچل و طوفان نے ایک نئی کرنسی "کرپٹو کرنسی" (Crypto Currency) کے نام سے دنیا میں چند سال قبل متعارف کرایا ہے، اس کرنسی کا تصور پیش کرنے والے یا موجد کا نام "ستوشی ناکا موتو" (Satoshinakamoto) بتایا جاتاہے، یہ کوئی شخص ہے یا ادارہ اس کی تفصیل کسی کو معلوم نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ کرۂ ارض پر کئی ایسی شخصیات موجود ہیں جو ستوشی ہونے کی دعویدار ہیں، بہر کیف دعوی کرنے والے ہوں یا کوئی بھی شخص جو بھی ہو اس کے بارے میں بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ وہ عصر حاضر کا ذہین ترین انسان ہے۔
کرپٹو کرنسی کی حقیقت بس یہ ہے کہ یہ ایک ڈیجیٹل اور نظر نہ آنے والی ایسی کرنسی ہے جسے نہ ہاتھوں میں لیا جاسکتا ہے نہ جیب میں رکھا جا سکتا ہے، گویا باہری دنیا میں اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، کمپیوٹر کی دنیا تک ہی یہ کرنسی محدود ہے، جو اکاؤنٹ ہولڈر کے اکاؤنٹ میں عددوں اور الفاظ کی شکل میں موجود رہتی ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انسان اس سے اپنے وہ تمام کام پورے کر سکتا ہے جو ہاتھوں میں پکڑے جانے والی اور جیبوں میں رکھی جانے والی کرنسی سے کرنا ممکن ہے، بآسانی بس یوں سمجھئے کہ جیسے ڈیبٹ
*(بٹ کوائن (Bit Coin) اور ون کوائن (Onecoin) پر ایک نظر)*
*از قلم: محمد زبیر الندوی*
*مركز البحث والإفتاء ممبئی انڈیا*
رابطہ 9029189288
جس طرح انسانی زندگی میں مختلف تبدیلیاں اور نیرنگیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں؛ اسی طرح کائنات کا نظام اور چیزیں بھی ان تبدیلیوں سے دو چار اور متاثر ہوتی رہتی ہیں، اسی لئے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی کسی شی کو دوام نہیں، مثل مشہور ہے "ہر کمالے را زوالے" ہر کمال کو زوال سے ضرور دوچار ہونا پڑتا ہے۔
آجکل ہمارے ہاتھوں میں جو کرنسی کی شکل میں پیسے یا روپئے موجود ہیں؛ ان کی کہانی بھی بڑی عجیب اور ان پر آنے والی تبدیلیاں بڑی حیرت انگیز ہیں، نوع انسانی کے ابتدائی دور اور بعد کے ادوار میں ایک طویل عرصہ ایسا گزرا ہے جب سونا چاندی اور روپئے پیسے کا بطور تبادلہ کوئی خیال تک نہ تھا، اس دور میں اشیاء کا تبادلہ اشیاء سے ہوتا تھا، چاول دیکر گیہوں لے لینا اور آٹا دے کر دودھ لے لینا ہی چیزوں کی خرید و فروخت کی مانی جانی شکل تھی، پھر ایک دور آیا کہ یہی تبادلہ سونے چاندی جیسی بیش قیمت دھاتوں سے ہونے لگا، انہیں کے ذریعے چیزیں خریدی اور فروخت کی جانے لگیں؛ لیکن بہت مدت نہیں گزری کہ خرید و فروخت کی دراز دستی نے سونے چاندی کے خول سے نکل کر ان سے بنے سکوں اور مختلف دھاتوں سے بنے پیسوں کی شکل اختیار کر لی۔
پھر ان کے بعد ایک ایسا بھی دور آیا جب لوگ سونے چاندی اور ان کے سکوں کو صرافوں کے پاس رکھ دیتے اور ان سے اس کی رسیدیں حاصل کرلیتے اور بوقت ضرورت رسید دکھا کر وہ سکے واپس لے لئے جاتے اور اگر کسی کو دینے کی ضرورت پیش آتی تو بعض فرزانے ایسا بھی کرتے کہ وہی رسید کسی اور کو دے دیتے اور وہ رسید دکھا کر صراف سے سونا لے لیتا، اور کبھی کبھی انہیں رسیدوں سے لوگ اشیاء کی خرید و فروخت کا معاملہ بھی کر لیتے، آہستہ آہستہ یہ سلسلہ عام اور دراز سے دراز تر ہوتا گیا، یہی وہ دور ہے جس کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ یہ نوٹوں کے آغاز کا ابتدائی زمانہ تھا اور جس کی اعلی ترین شکل اب ہمارے زمانے میں اس قدر عام ہے کہ اس کے خلاف سوچنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔
کرنسی نوٹ کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جوں جوں اس میں ترقی ہوتی گئی یہ اپنی اصلیت یعنی "ثمن حقیقی" سے دور سے دور تر ہوتی چلی گئی، کسی زمانے میں ان کرنسیوں کے پیچھے سو فیصد سونا ہوا کرتا تھا، پھر ایک زمانہ آیا کہ انہیں ڈالر سے جوڑ دیا گیا اور ڈالر کے پیچھے سونا تسلیم کر لیا گیا تھا، گویا بالواسطہ ان کے پیچھے سونا موجود تھا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کرنسیوں نے ڈالر سے بھی اپنا دامن چھڑا لیا اور اب ہم جس کرنسی کے دیوانے ہیں اور جس کی دستیابی کے لئے مر مٹ رہے ہیں اس کا سونے چاندی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے اور سوائے اس کی کہ اسے قانونی طور پر خرید و فروخت کا ایک ذریعہ تسلیم کر لیا گیا ہے اس کی حیثیت ایک کاغذ سے زیادہ نہیں۔
مگر جیسا کہ اوپر ذکر ہوا "ہر کمالے را زوالے" کچھ انسانوں کو شاید یہ سکے اور کاغذی نوٹ بھی بوجھ معلوم ہو رہے تھے یا یوں کہہ لیجیے کہ کرنسی نے ایک نئی انقلابی کروٹ لی اور اب ایک ایسی کرنسی وجود میں آچکی ہے؛ جسے جیب میں رکھنے اور چور اچکوں سے محفوظ رکھنے کی فکر دامن گیر نہ ہو گی، اس کرنسی سے انسان اپنی تمام تر ضروریات کی تکمیل بھی کر سکے گا اور پیسوں، سکوں کے بوجھت سے بھی آزاد ہوگا، ذیل میں اسی کرنسی سے متعلق چند اہم معلومات فراہم کی جاتی ہیں امید کہ اس تحریر سے اس نومولود کرنسی کو سمجھنا آسان ہوگا۔
اس وقت تمام دنیا میں آن لائن کارو بار کا جو طوفان برپا ہوا ہے اور معیشت و تجارت میں جو زبردست ہلچل اور گہما گہمی پیدا ہوئی ہے شاید ماضی کے کسی زمانے میں پیدا نہیں ہوئی ہوگی، اسی ہلچل و طوفان نے ایک نئی کرنسی "کرپٹو کرنسی" (Crypto Currency) کے نام سے دنیا میں چند سال قبل متعارف کرایا ہے، اس کرنسی کا تصور پیش کرنے والے یا موجد کا نام "ستوشی ناکا موتو" (Satoshinakamoto) بتایا جاتاہے، یہ کوئی شخص ہے یا ادارہ اس کی تفصیل کسی کو معلوم نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ کرۂ ارض پر کئی ایسی شخصیات موجود ہیں جو ستوشی ہونے کی دعویدار ہیں، بہر کیف دعوی کرنے والے ہوں یا کوئی بھی شخص جو بھی ہو اس کے بارے میں بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ وہ عصر حاضر کا ذہین ترین انسان ہے۔
کرپٹو کرنسی کی حقیقت بس یہ ہے کہ یہ ایک ڈیجیٹل اور نظر نہ آنے والی ایسی کرنسی ہے جسے نہ ہاتھوں میں لیا جاسکتا ہے نہ جیب میں رکھا جا سکتا ہے، گویا باہری دنیا میں اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، کمپیوٹر کی دنیا تک ہی یہ کرنسی محدود ہے، جو اکاؤنٹ ہولڈر کے اکاؤنٹ میں عددوں اور الفاظ کی شکل میں موجود رہتی ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انسان اس سے اپنے وہ تمام کام پورے کر سکتا ہے جو ہاتھوں میں پکڑے جانے والی اور جیبوں میں رکھی جانے والی کرنسی سے کرنا ممکن ہے، بآسانی بس یوں سمجھئے کہ جیسے ڈیبٹ
کارڈ میں حقیقتا کچھ ہوتا نہیں ہے مگر اس کے ذریعے کارڈ ہولڈر اپنی ضروریات خرید کر اکاؤنٹ میں موجود بیلنس یا بینک سے ادھار لے کر قیمت ادا کر سکتا ہے ایسے ہی اس کرنسی سے بھی سارے معاملات اخاونٹ اور خارڈ سے انجام دییے جاسکتے ہیں۔
اس کرنسی کی متعدد قسمیں اور اکائیاں آن لائن مارکیٹ میں آچکی ہیں، مگر اس کی سب سے قیمتی اور مشہور ترین کرنسی بٹ کوائن (Bit Coin) اور ون کوائن (Onecoin) ہیں، ان کی قیمت اس قدر زیادہ ہے کہ دنیا کی موجودہ کوئی کرنسی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آپ کو شاید حیرت ہو کہ ایک بٹ کوائن کی قیمت آٹھ لاکھ روپئے سے متجاوز جبکہ ایک ون کوائن کی قیمت تیرہ سو روپے زائد ہے۔
مزید تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کرنسی پر کسی ایک شخص یا ملک یا بینک کا قبضہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایک شخص یا بینک یا کمپنی اس کو کنٹرول کرتی ہے، بلکہ یہ لوگوں کے تعامل سے جاری اور قائم ہے، اسے کوئی بھی شخص یا ادارہ بنا سکتا ہے، کرپٹو کرنسی کی اصطلاح میں اس کے بنانے کو مائننگ (Mining) کہا جاتا ہے، جس کا لفظی ترجمہ ہے "کان کھودنا" یعنی جس طرح زمین سے کانیں کھود کر اس کی تہ سے بیش قیمت چیزیں نکالی جاتی ہیں اسی طرح نہایت طاقتور اور خاص قسم کے پروگرامنگ والے کمپیوٹر اور مسلسل بجلی کے ذریعے مخصوص الفاظ اور نمبرات سے اس کی بناوٹ عمل میں آتی ہے، شروع شروع میں اس کی مائننگ بہت آسان تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا اور قیمت بڑھتی جاتی ہے اس کی مائننگ مشکل سے مشکل تر ہوتی جارہی ہے، اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ بٹ کوائن جیسی کرپٹو کرنسی ایک محدود تعداد (دو کروڑ دس لاکھ) ہی بنائے جا سکتے ہیں اور اتنے کوائن بنانے کے لئے 2150 ء تک کا وقت لگے گا، اس سے پہلے یہ سکے مکمل نہیں کئے جاسکتے، اس کی مائننگ کرنے والوں کو بطور انعام بٹس ہی دیئے جاتے ہیں جسے وہ گاہکوں سے بیچ کر نفع کماتے اور سسٹم کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔
اس سلسلے میں ایک نہایت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کرنسی کی جتنی خرید و فروخت ہوتی ہے یا جو بھی معاملات اور ٹرانزکشن ہوتے ہیں وہ ہر دس منٹ میں ایک مخصوص جگہ محفوظ ہوجاتے ہیں اس پورے ٹرانزکشن کے مجموعے کو بلاکس (Blocks) کہا جاتا ہے، اس کرنسی کو گرچہ ابھی عام قبولیت حاصل نہیں ہوئی ہے تاہم متعدد ملکوں نے اپنے باشندوں کے لئے اسے لیگل قرار دے دیا ہے اور وہاں کے لوگ اس سے اپنے کام انجام دے رہے ہیں جاپان جیسے ترقی یافتہ ملک میں اس کے اے ٹی ایم ATM بھی لگائے جاچکے ہیں بلکہ راقم الحروف کی دانست میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے یہاں اسے ابھی قبول نہیں کیا گیا ہے مگر وہ اسے خریدنے کی وجہ سے بہت سے کام اسی سے کر رہے ہیں۔ اس کرنسی کے متعدد فائدے بتائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہی اس کی مہنگائی کے اسباب ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق چند دہائیوں میں یہی کرنسی عالمی کرنسی ہوگی۔ اس کے فوائد مندرجہ ذیل ہیں:
1 اس کرنسی کے ذریعے آدمی ان بڑی بڑی کمپنیوں سے سامان خرید سکتا ہے جو بٹ کوائن یا ون کوائن میں حصہ دار ہیں۔
2 اس کرنسی کے ذریعے پوری دنیا میں کسی بھی شخص کو اپنے اکاؤنٹ سے بغیر کسی کمپنی یا بینک کو واسطہ بنائے رقم منتقل کی جا سکتی ہے۔
3 رسد کی کمی اور طلب کی زیادتی یعنی کوائن کی کمی اور خریداروں کی کثرت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے اور اس طرح آپ کی کرنسی مہنگی ہوتی جاتی ہے۔
4 اگر آپ خود بٹ کوائن یا ون کوائن سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے ہیں تو بڑھی ہوئی رقم کے مطابق بیچ سکتے ہیں اور اس طرح آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوسکتا ہے۔
5 آپ جب چاہیں اپنی کرنسی کو ملکی کرنسی میں تبدیل کرا سکتے ہیں۔
6 اس کرنسی کو نہ کوئی چرا سکتا ہے نہ ہی غائب کر سکتا ہے، نیز اس سے ٹرانزکشن اس قدر آسان ہے کہ گھر بیٹھے انٹر نیٹ سے ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں۔
7 چونکہ اس کا تعلق کسی بینک یا ادارہ سے نہیں ہے اس لئے دوسرے کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کرنے کے لئے بہت ہی کم رقم لگتی ہے۔
8 چونکہ یہ کرنسی decentralised ہے اس لئے اس کرنسی کو کوئی ملک نہ بند کر سکتا ہے اور نہ ہی ہائک کر سکتا ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے ملک میں جاری نہ کرے جیسا کہ ہندوستان وغیرہ میں ہے۔
اس موقع پر یہ واضح کر دینا بھی نہایت ضروری ہے کہ جہاں کرپٹو کرنسی کے اس قدر فائدے ہیں وہیں کچھ نقصانات بھی ہیں اور پھر دنیا کی کونسی ایسی چیز ہے جس کے دونوں پہلو نہ ہوں؟ چنانچہ اس کرنسی لینے کا ایک نقصان یہ ہےکہ چونکہ اسے اپنے ہاتھ یا جیب میں رکھا نہیں جاسکتا ہے اور صرف انٹرنیٹ ہی کی ذریعے اس کا استعمال ممکن ہے؛ اس لئے آپ عام لوگوں سے کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی بوقت ضرورت ہر کس و ناکس سے لین دین کا معاملہ کر سکتے ہیں۔
دوسرا نقصان یہ ہے کہ چونکہ یہ ڈیجیٹل چیز ہے اگر بالاتفاق بیک وقت تمام ڈیجیٹل سسٹم فیل ہو جائے یا کسی ظالم طاقتور کا غاصبانہ قبضہ ہو جائے تو آپ کی لگائی رقم بالکل ختم ہو سکتی ہے
اس کرنسی کی متعدد قسمیں اور اکائیاں آن لائن مارکیٹ میں آچکی ہیں، مگر اس کی سب سے قیمتی اور مشہور ترین کرنسی بٹ کوائن (Bit Coin) اور ون کوائن (Onecoin) ہیں، ان کی قیمت اس قدر زیادہ ہے کہ دنیا کی موجودہ کوئی کرنسی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آپ کو شاید حیرت ہو کہ ایک بٹ کوائن کی قیمت آٹھ لاکھ روپئے سے متجاوز جبکہ ایک ون کوائن کی قیمت تیرہ سو روپے زائد ہے۔
مزید تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کرنسی پر کسی ایک شخص یا ملک یا بینک کا قبضہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایک شخص یا بینک یا کمپنی اس کو کنٹرول کرتی ہے، بلکہ یہ لوگوں کے تعامل سے جاری اور قائم ہے، اسے کوئی بھی شخص یا ادارہ بنا سکتا ہے، کرپٹو کرنسی کی اصطلاح میں اس کے بنانے کو مائننگ (Mining) کہا جاتا ہے، جس کا لفظی ترجمہ ہے "کان کھودنا" یعنی جس طرح زمین سے کانیں کھود کر اس کی تہ سے بیش قیمت چیزیں نکالی جاتی ہیں اسی طرح نہایت طاقتور اور خاص قسم کے پروگرامنگ والے کمپیوٹر اور مسلسل بجلی کے ذریعے مخصوص الفاظ اور نمبرات سے اس کی بناوٹ عمل میں آتی ہے، شروع شروع میں اس کی مائننگ بہت آسان تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا اور قیمت بڑھتی جاتی ہے اس کی مائننگ مشکل سے مشکل تر ہوتی جارہی ہے، اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ بٹ کوائن جیسی کرپٹو کرنسی ایک محدود تعداد (دو کروڑ دس لاکھ) ہی بنائے جا سکتے ہیں اور اتنے کوائن بنانے کے لئے 2150 ء تک کا وقت لگے گا، اس سے پہلے یہ سکے مکمل نہیں کئے جاسکتے، اس کی مائننگ کرنے والوں کو بطور انعام بٹس ہی دیئے جاتے ہیں جسے وہ گاہکوں سے بیچ کر نفع کماتے اور سسٹم کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔
اس سلسلے میں ایک نہایت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کرنسی کی جتنی خرید و فروخت ہوتی ہے یا جو بھی معاملات اور ٹرانزکشن ہوتے ہیں وہ ہر دس منٹ میں ایک مخصوص جگہ محفوظ ہوجاتے ہیں اس پورے ٹرانزکشن کے مجموعے کو بلاکس (Blocks) کہا جاتا ہے، اس کرنسی کو گرچہ ابھی عام قبولیت حاصل نہیں ہوئی ہے تاہم متعدد ملکوں نے اپنے باشندوں کے لئے اسے لیگل قرار دے دیا ہے اور وہاں کے لوگ اس سے اپنے کام انجام دے رہے ہیں جاپان جیسے ترقی یافتہ ملک میں اس کے اے ٹی ایم ATM بھی لگائے جاچکے ہیں بلکہ راقم الحروف کی دانست میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے یہاں اسے ابھی قبول نہیں کیا گیا ہے مگر وہ اسے خریدنے کی وجہ سے بہت سے کام اسی سے کر رہے ہیں۔ اس کرنسی کے متعدد فائدے بتائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہی اس کی مہنگائی کے اسباب ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق چند دہائیوں میں یہی کرنسی عالمی کرنسی ہوگی۔ اس کے فوائد مندرجہ ذیل ہیں:
1 اس کرنسی کے ذریعے آدمی ان بڑی بڑی کمپنیوں سے سامان خرید سکتا ہے جو بٹ کوائن یا ون کوائن میں حصہ دار ہیں۔
2 اس کرنسی کے ذریعے پوری دنیا میں کسی بھی شخص کو اپنے اکاؤنٹ سے بغیر کسی کمپنی یا بینک کو واسطہ بنائے رقم منتقل کی جا سکتی ہے۔
3 رسد کی کمی اور طلب کی زیادتی یعنی کوائن کی کمی اور خریداروں کی کثرت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے اور اس طرح آپ کی کرنسی مہنگی ہوتی جاتی ہے۔
4 اگر آپ خود بٹ کوائن یا ون کوائن سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے ہیں تو بڑھی ہوئی رقم کے مطابق بیچ سکتے ہیں اور اس طرح آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوسکتا ہے۔
5 آپ جب چاہیں اپنی کرنسی کو ملکی کرنسی میں تبدیل کرا سکتے ہیں۔
6 اس کرنسی کو نہ کوئی چرا سکتا ہے نہ ہی غائب کر سکتا ہے، نیز اس سے ٹرانزکشن اس قدر آسان ہے کہ گھر بیٹھے انٹر نیٹ سے ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں۔
7 چونکہ اس کا تعلق کسی بینک یا ادارہ سے نہیں ہے اس لئے دوسرے کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کرنے کے لئے بہت ہی کم رقم لگتی ہے۔
8 چونکہ یہ کرنسی decentralised ہے اس لئے اس کرنسی کو کوئی ملک نہ بند کر سکتا ہے اور نہ ہی ہائک کر سکتا ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے ملک میں جاری نہ کرے جیسا کہ ہندوستان وغیرہ میں ہے۔
اس موقع پر یہ واضح کر دینا بھی نہایت ضروری ہے کہ جہاں کرپٹو کرنسی کے اس قدر فائدے ہیں وہیں کچھ نقصانات بھی ہیں اور پھر دنیا کی کونسی ایسی چیز ہے جس کے دونوں پہلو نہ ہوں؟ چنانچہ اس کرنسی لینے کا ایک نقصان یہ ہےکہ چونکہ اسے اپنے ہاتھ یا جیب میں رکھا نہیں جاسکتا ہے اور صرف انٹرنیٹ ہی کی ذریعے اس کا استعمال ممکن ہے؛ اس لئے آپ عام لوگوں سے کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی بوقت ضرورت ہر کس و ناکس سے لین دین کا معاملہ کر سکتے ہیں۔
دوسرا نقصان یہ ہے کہ چونکہ یہ ڈیجیٹل چیز ہے اگر بالاتفاق بیک وقت تمام ڈیجیٹل سسٹم فیل ہو جائے یا کسی ظالم طاقتور کا غاصبانہ قبضہ ہو جائے تو آپ کی لگائی رقم بالکل ختم ہو سکتی ہے
تیسرا نقصان یہ ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے اسے لیگل نہیں کیا ہے وہاں کا باشندہ اگر اسے لیتا ہے اور کوئی بات پیش آجاتی ہے تو وہ اپنے ملک میں استغاثہ نہیں کر سکتا ہے ہاں دوسرے ملک سے چانس پھر بھی رہتا ہے۔
چوتھا یہ کہ جس طرح اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے اندیشہ ہے کہ کبھی بہت کم یا بالکل کم ہوجائے اور آپ کو نقصان ہوجائے۔
کرپٹو کرنسی کے بارے میں مذکورہ بالا چار نقصانات متوقع اور ممکن ہیں؛ گرچہ ابھی تک ایسا کچھ ہوا نہیں ہے اور قرائن و آثار سے بھی اس کی مضبوطی اور استحکام ہی معلوم ہوتی ہے؛ مگر اندیشوں سے باخبر کرنا اور باخبر رہنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ یہ دانشمندی کی علامت ہے بقول شاعر مشرق:
*امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے*
اس کرنسی کی خریداری یا شراکت کے بارے میں قارئین کو یہ بتا دینا ضروری ہے کہ چونکہ یہ ایک نہایت مہنگی کرنسی ہے؛ اس لئے اگر کوئی شخص مکمل ایک بٹ نہ خرید سکے تو اس کا کچھ حصہ بھی خرید سکتا ہے، اس میں شرکت کے لئے لوگوں کی آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف پیکیج بنائے گئے ہیں اور ہر پیکیج پر ملنے والا نفع بھی الگ الگ ہے، مثلا بٹ کوائن کا سب سے چھوٹا پیکیج گیارہ ہزار کا ہے، اس پر ملنے والی رقم ہر ماہ 500 سے 1000 تک متوقع ہے، دوسرا پیکیج 41000 روپئے کا ہے اس پر ملنے والا نفع ہر 21 دن میں 3000 سے 4000 تک ہے، تیسرا پیکیج 78000 روپئے کا ہے اس پر ملنے والا نفع ہر 19 دن میں 6000 سے 8000 تک ہے۔ لیکن واضح رہے کہ اگر کوائن کی قیمت کم ہوگئی تو آپ کو اس سے بھی کم نفع مل سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ بھی نہ ملے، اس لئے نفع و نقصان دونوں پہلو اس میں موجود ہیں۔ اس وقت کرپٹو کرنسی کی جو عام نوعیت ہے وہ یہی ہے جو اس پوری تحریر میں بیان ہوئی، ابھی اس سلسلے میں کوئی متعین شرعی نقطہ نظر قائم نہیں کیا گیا ہے، لیکن جلد ہی قارئین کو حکم شرعی سے مطلع کیا جائے گا ۔
*نوٹ:* اہل علم حضرات سے گزارش ہے کہ اس تحریر کی روشنی میں شرعی نقطہ نظر تک پہونچنے کی کوشش کریں اور ممکن ہو تو مزید اس موضوع پر تحقیق کریں اور مسلمانوں کو صحیح شرعی نقطہ نظر سے آگاہ کریں کیونکہ یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ فجزاکم اللہ خیر الجزاء۔
چوتھا یہ کہ جس طرح اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے اندیشہ ہے کہ کبھی بہت کم یا بالکل کم ہوجائے اور آپ کو نقصان ہوجائے۔
کرپٹو کرنسی کے بارے میں مذکورہ بالا چار نقصانات متوقع اور ممکن ہیں؛ گرچہ ابھی تک ایسا کچھ ہوا نہیں ہے اور قرائن و آثار سے بھی اس کی مضبوطی اور استحکام ہی معلوم ہوتی ہے؛ مگر اندیشوں سے باخبر کرنا اور باخبر رہنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ یہ دانشمندی کی علامت ہے بقول شاعر مشرق:
*امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے*
اس کرنسی کی خریداری یا شراکت کے بارے میں قارئین کو یہ بتا دینا ضروری ہے کہ چونکہ یہ ایک نہایت مہنگی کرنسی ہے؛ اس لئے اگر کوئی شخص مکمل ایک بٹ نہ خرید سکے تو اس کا کچھ حصہ بھی خرید سکتا ہے، اس میں شرکت کے لئے لوگوں کی آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف پیکیج بنائے گئے ہیں اور ہر پیکیج پر ملنے والا نفع بھی الگ الگ ہے، مثلا بٹ کوائن کا سب سے چھوٹا پیکیج گیارہ ہزار کا ہے، اس پر ملنے والی رقم ہر ماہ 500 سے 1000 تک متوقع ہے، دوسرا پیکیج 41000 روپئے کا ہے اس پر ملنے والا نفع ہر 21 دن میں 3000 سے 4000 تک ہے، تیسرا پیکیج 78000 روپئے کا ہے اس پر ملنے والا نفع ہر 19 دن میں 6000 سے 8000 تک ہے۔ لیکن واضح رہے کہ اگر کوائن کی قیمت کم ہوگئی تو آپ کو اس سے بھی کم نفع مل سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ بھی نہ ملے، اس لئے نفع و نقصان دونوں پہلو اس میں موجود ہیں۔ اس وقت کرپٹو کرنسی کی جو عام نوعیت ہے وہ یہی ہے جو اس پوری تحریر میں بیان ہوئی، ابھی اس سلسلے میں کوئی متعین شرعی نقطہ نظر قائم نہیں کیا گیا ہے، لیکن جلد ہی قارئین کو حکم شرعی سے مطلع کیا جائے گا ۔
*نوٹ:* اہل علم حضرات سے گزارش ہے کہ اس تحریر کی روشنی میں شرعی نقطہ نظر تک پہونچنے کی کوشش کریں اور ممکن ہو تو مزید اس موضوع پر تحقیق کریں اور مسلمانوں کو صحیح شرعی نقطہ نظر سے آگاہ کریں کیونکہ یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ فجزاکم اللہ خیر الجزاء۔
*جبراً زبانی اور تحریری طلاق میں فرق*
سوال
کیا فرماتے ہیں علماءِ کرام ومفتیانِ عظام اس مسئلہ کے بارے میں کہ جبراً طلاق دلوانے یا لکھوانے سے طلاق واقع ہوتی ہےیا نہیں اور جبرکی تعریف کیا ہے؟
*الجواب بعون الملک الوھاب*
صورت مسئولہ میں جبراً طلاق دلوانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے البتہ جبراً طلاق لکھوانے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ بشرطیکہ لکھتے وقت زبان سے کچھ نہ کہا جائے، اگر لکھتے وقت زبان سے الفاظ ِ طلاق ادا کئے تو پھر طلاق واقع ہوجائے گی نیز اصطلاحِ شریعت میں جبراً طلاق کی تعریف یہ ہے کہ دھمکی دینے والا جان سے مار ڈالنے یا کسی عضو کے تلف کرنے کی دھمکی دے اور وہ اس پر قادر ہو اور جس کو دھمکی دی جارہی ہے اس کو یقین ہو یا غالب گمان ہو کہ اگر میں نے طلاق نہ دی تو مجھے مار دیا جائے گا یا کوئی عضو تلف کردیا جائے گا تو ایسی طلاق کو جبراً طلاق کہتے ہیں ۔
لمافی سنن ابی داؤد (۲۹۸/۱):
عن أبى هريرة ؓ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة ۔
وفی الھندیۃ (۳۵۳/۱):
فصل فيمن يقع طلاقه وفيمن لا يقع طلاقه يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغا عاقلا سواء كان حرا أو عبدا طائعا أو مكرها كذا في الجوهرة النيرة۔
وفیہ أیضا (۳۷۹/۱):
رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان بن فلان فكتب امرأته فلانة بنت فلان بن فلان طالق لا تطلق امرأته كذا في فتاوى قاضي خان۔
وفی الشامیۃ (۲۳۶/۳):هذا وفي البحر أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا كذا في الخانية۔
واللہ اعلم بالصواب
محمد مصروف مظاہری
سوال
کیا فرماتے ہیں علماءِ کرام ومفتیانِ عظام اس مسئلہ کے بارے میں کہ جبراً طلاق دلوانے یا لکھوانے سے طلاق واقع ہوتی ہےیا نہیں اور جبرکی تعریف کیا ہے؟
*الجواب بعون الملک الوھاب*
صورت مسئولہ میں جبراً طلاق دلوانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے البتہ جبراً طلاق لکھوانے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ بشرطیکہ لکھتے وقت زبان سے کچھ نہ کہا جائے، اگر لکھتے وقت زبان سے الفاظ ِ طلاق ادا کئے تو پھر طلاق واقع ہوجائے گی نیز اصطلاحِ شریعت میں جبراً طلاق کی تعریف یہ ہے کہ دھمکی دینے والا جان سے مار ڈالنے یا کسی عضو کے تلف کرنے کی دھمکی دے اور وہ اس پر قادر ہو اور جس کو دھمکی دی جارہی ہے اس کو یقین ہو یا غالب گمان ہو کہ اگر میں نے طلاق نہ دی تو مجھے مار دیا جائے گا یا کوئی عضو تلف کردیا جائے گا تو ایسی طلاق کو جبراً طلاق کہتے ہیں ۔
لمافی سنن ابی داؤد (۲۹۸/۱):
عن أبى هريرة ؓ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة ۔
وفی الھندیۃ (۳۵۳/۱):
فصل فيمن يقع طلاقه وفيمن لا يقع طلاقه يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغا عاقلا سواء كان حرا أو عبدا طائعا أو مكرها كذا في الجوهرة النيرة۔
وفیہ أیضا (۳۷۹/۱):
رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان بن فلان فكتب امرأته فلانة بنت فلان بن فلان طالق لا تطلق امرأته كذا في فتاوى قاضي خان۔
وفی الشامیۃ (۲۳۶/۳):هذا وفي البحر أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا كذا في الخانية۔
واللہ اعلم بالصواب
محمد مصروف مظاہری
ٹیوی دیکھنا
الجواب حامدا ومصلیا:
ٹی وی دیکھنے سے متعلق شرعی حکم جاننے سے پہلے ویڈیو سے متعلق شرعی حکم سمجھنا چاہیے، شریعت نے جانداروں سے متعلق جس قسم کی تصویر کو حرام قرار دیا ہے٫ کیا ویڈیو بھی اس تصویر کے حکم میں داخل ہے یا نہیں، اس میں حضراتِ اکابر اہلِ علم کی دو آرا ہیں: ایک رائے یہ ہے کہ ویڈیو اسی ممنوع تصویر کا حکم رکھتی ہے٫ اس رائے کے مطابق جانداروں کی عکس بندی سے متعلق ویڈیو میں اگرچہ بظاہر کوئی ناجائز بات نہ بھی ہو لیکن اس کا تصویر پر مشتمل ہونا ہی ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے.
دوسری رائے جامعہ دارالعلوم کراچی اور دیگر متعدد اہل علم کی ہے کہ ویڈیو ممنوعہ تصویر کے حکم میں نہیں، اس رائے کے مطابق ایسی ویڈیو جس میں کوئی غیر شرعی کام نہ ہو تو ایسی ویڈیو کا دیکھنا درست ہے۔
جس شخص کو ان اکابر اہل علم میں سے جن پر اعتماد ہو وہ انہی کی رائے پر عمل کرے،
اس تفصیل کے تناظر میں ٹی وی کو بھی ویڈیو کے اس حکم پر قیاس کیا جانا چاہیے٫ البتہ یہ بات تو بالکل حقیقت ہے کہ ٹی وی میں ایسے پروگرام کی بڑی ہی قلت ہے جس میں شریعت کا کوئی بھی حکم پامال نہ ہوتا ہو٫ بلکہ میوزک، بے حیائی، خواتین کی بہتات اور ان جیسے دیگر اخلاقی اور نظریاتی فساد کے اسباب پر مشتمل پروگراموں کی کثرت ہے، جس کی وجہ سے موجودہ حالات میں ٹی وی دیکھتے رہنے میں گناہوں سے بچنا مشکل ہے، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے خصوصا ٹی وی گھر لانا درحقیقت واضح طور پر گناہوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے جس کا مشورہ کوئی نہیں دے سکتا، اور جائز ویڈیو کا جائز قرار دینے والے اہل علم بھی ٹی وی سے اجتناب کرنے کا کہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ٹی وی کو محض ویڈیو کے تناظر میں نہ دیکھا جائے بلکہ یہ بہت سے مفاسد پر مشتمل ایک خاموش پالیسی ہے٫ جس سے کسی کو انکار نہیں ہوسکتا.
اس لیے یوں کہنا زیادہ مناسب ہے کہ اصل مسئلہ ٹی وی دیکھنے یا نہ دیکھنے کا نہیں٫ بلکہ ان کاموں سے بچنے کا ہے جن سے شریعت نے منع کیا ہے٫ خواہ ٹی وی میں ہوں یا عام ویڈیو میں ہوں یا دیگر زندگی میں.
واللہ تعالی اعلم۔۔۔۔
مبین الرحمن
الجواب حامدا ومصلیا:
ٹی وی دیکھنے سے متعلق شرعی حکم جاننے سے پہلے ویڈیو سے متعلق شرعی حکم سمجھنا چاہیے، شریعت نے جانداروں سے متعلق جس قسم کی تصویر کو حرام قرار دیا ہے٫ کیا ویڈیو بھی اس تصویر کے حکم میں داخل ہے یا نہیں، اس میں حضراتِ اکابر اہلِ علم کی دو آرا ہیں: ایک رائے یہ ہے کہ ویڈیو اسی ممنوع تصویر کا حکم رکھتی ہے٫ اس رائے کے مطابق جانداروں کی عکس بندی سے متعلق ویڈیو میں اگرچہ بظاہر کوئی ناجائز بات نہ بھی ہو لیکن اس کا تصویر پر مشتمل ہونا ہی ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے.
دوسری رائے جامعہ دارالعلوم کراچی اور دیگر متعدد اہل علم کی ہے کہ ویڈیو ممنوعہ تصویر کے حکم میں نہیں، اس رائے کے مطابق ایسی ویڈیو جس میں کوئی غیر شرعی کام نہ ہو تو ایسی ویڈیو کا دیکھنا درست ہے۔
جس شخص کو ان اکابر اہل علم میں سے جن پر اعتماد ہو وہ انہی کی رائے پر عمل کرے،
اس تفصیل کے تناظر میں ٹی وی کو بھی ویڈیو کے اس حکم پر قیاس کیا جانا چاہیے٫ البتہ یہ بات تو بالکل حقیقت ہے کہ ٹی وی میں ایسے پروگرام کی بڑی ہی قلت ہے جس میں شریعت کا کوئی بھی حکم پامال نہ ہوتا ہو٫ بلکہ میوزک، بے حیائی، خواتین کی بہتات اور ان جیسے دیگر اخلاقی اور نظریاتی فساد کے اسباب پر مشتمل پروگراموں کی کثرت ہے، جس کی وجہ سے موجودہ حالات میں ٹی وی دیکھتے رہنے میں گناہوں سے بچنا مشکل ہے، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے خصوصا ٹی وی گھر لانا درحقیقت واضح طور پر گناہوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے جس کا مشورہ کوئی نہیں دے سکتا، اور جائز ویڈیو کا جائز قرار دینے والے اہل علم بھی ٹی وی سے اجتناب کرنے کا کہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ٹی وی کو محض ویڈیو کے تناظر میں نہ دیکھا جائے بلکہ یہ بہت سے مفاسد پر مشتمل ایک خاموش پالیسی ہے٫ جس سے کسی کو انکار نہیں ہوسکتا.
اس لیے یوں کہنا زیادہ مناسب ہے کہ اصل مسئلہ ٹی وی دیکھنے یا نہ دیکھنے کا نہیں٫ بلکہ ان کاموں سے بچنے کا ہے جن سے شریعت نے منع کیا ہے٫ خواہ ٹی وی میں ہوں یا عام ویڈیو میں ہوں یا دیگر زندگی میں.
واللہ تعالی اعلم۔۔۔۔
مبین الرحمن
تعزیت کا طریقہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم
الجواب حامدًا ومصلّياً
واضح رہے کہ کسی شخص کے انتقال کے بعد تیسرے دن تک ایک بار میّت کے گھر والوں کے پاس جاکرتعزیت کرنا مسنون ہے اور حدیث میں اس پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔لہذا ایک حدیث میں آیا ہے:
"من عزى مصابا فله مثل أجره"
ترجمہ:" جس نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا مصیبت زدہ کو(مصیبت پہنچنے اور اس پر صبر کرنے پر ملےگا)"۔
اور تعزیت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اہل میّت کے پاس جایا جائے اور ان سے اظہارِ ہمدردی کرتے ہوئے ان کو تسکین اور تسلی دی جائے اور صبر کے فضائل اور اس کا عظیم اجر و ثواب سنا کر ان کو صبر کی تلقین کی جائے اور میت کے لئے دعاءِ مغفرت کی جائے۔
تاہم تعزیت کا مروّجہ طریقہ جس میں ہر آنے والے کے کہنے پر بار بار ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور لوگ اسی کو تعزیت سمجھتے ہیں،نیزایسا نہ کرنے والے کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ ناجائز اور بدعت ہے، نبی کریمﷺ، خلفاءراشدین ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ،تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں،لہذا اس سے بچنا لازم ہے ۔ (مأخذہ‘ التبویب:94/176)
ردّ المحتار(2/241،240)
فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: وَتُسْتَحَبُّ التَّعْزِيَةُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَفْتِنَّ، لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنْ عَزَّى أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. وَالتَّعْزِيَةُ أَنْ يَقُولَ: أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَك، وَأَحْسَنَ عَزَاءَك، وَغَفَرَ لِمَيِّتِك. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبِالْجُلُوسِ لَهَا) أَيْ لِلتَّعْزِيَةِ، وَاسْتِعْمَالُ لَا بَأْسَ هُنَا عَلَى حَقِيقَتِهِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ. وَفِي الْأَحْكَامِ عَنْ خِزَانَةِ الْفَتَاوَى: الْجُلُوسُ فِي الْمُصِيبَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلرِّجَالِ جَاءَتْ الرُّخْصَةُ فِيهِ، وَلَا تَجْلِسُ النِّسَاءُ قَطْعًا اهـ۔۔۔
وَفِي الْإِمْدَادِ: وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ مُتَأَخِّرِي أَئِمَّتِنَا يُكْرَهُ الِاجْتِمَاعُ عِنْدَ صَاحِبِ الْبَيْتِ وَيُكْرَهُ لَهُ الْجُلُوسُ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ إلَيْهِ مَنْ يُعَزِّي، بَلْ إذَا فَرَغَ وَرَجَعَ النَّاسُ مِنْ الدَّفْنِ فَلْيَتَفَرَّقُوا وَيَشْتَغِلُ النَّاسُ بِأُمُورِهِمْ وَصَاحِبُ الْبَيْتِ بِأَمْرِهِ اهـ۔۔۔ (قَوْلُهُ وَتُكْرَهُ التَّعْزِيَةُ ثَانِيًا) فِي التَّتَارْخَانِيَّة: لَا يَنْبَغِي لِمَنْ عَزَّى مَرَّةً أَنْ يُعَزِّيَ مَرَّةً أُخْرَى رَوَاهُ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ. اهـ. إمْدَادٌ۔
تبیین الحقائق مع حاشية الشِّلبیّ(1/246)
[فصل تعزية أهل الميت]
(فصل) ولا بأس بتعزية أهل الميت وترغيبهم في الصبر لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من عزى مصابا فله مثل أجره» ويقول له أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاءك وغفر لميتك ، ولا بأس بالجلوس لها إلى ثلاثة أيام من غير ارتكاب محظور من فرش البسط والأطعمة من أهل الميت ؛ لأنها تتخذ عند السرور۔۔۔
(قوله : لا بأس بتعزية أهل الميت إلخ) ، وأكثرهم على أن يعزى إلى ثلاثة أيام ثم يترك لئلا يتجدد الحزن وروى ابن ماجه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة»۔
فتح الباري لابن حجر - (13 / 253)
والمحدثات بفتح الدال جمع محدثة والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعة وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما وكذا القول في المحدثة وفي الأمر المحدث الذي ورد في حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔۔ و اللہ تعالیٰ اعلم
بسم اللہ الرحمن الرحیم
الجواب حامدًا ومصلّياً
واضح رہے کہ کسی شخص کے انتقال کے بعد تیسرے دن تک ایک بار میّت کے گھر والوں کے پاس جاکرتعزیت کرنا مسنون ہے اور حدیث میں اس پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔لہذا ایک حدیث میں آیا ہے:
"من عزى مصابا فله مثل أجره"
ترجمہ:" جس نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا مصیبت زدہ کو(مصیبت پہنچنے اور اس پر صبر کرنے پر ملےگا)"۔
اور تعزیت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اہل میّت کے پاس جایا جائے اور ان سے اظہارِ ہمدردی کرتے ہوئے ان کو تسکین اور تسلی دی جائے اور صبر کے فضائل اور اس کا عظیم اجر و ثواب سنا کر ان کو صبر کی تلقین کی جائے اور میت کے لئے دعاءِ مغفرت کی جائے۔
تاہم تعزیت کا مروّجہ طریقہ جس میں ہر آنے والے کے کہنے پر بار بار ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور لوگ اسی کو تعزیت سمجھتے ہیں،نیزایسا نہ کرنے والے کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ ناجائز اور بدعت ہے، نبی کریمﷺ، خلفاءراشدین ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ،تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں،لہذا اس سے بچنا لازم ہے ۔ (مأخذہ‘ التبویب:94/176)
ردّ المحتار(2/241،240)
فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: وَتُسْتَحَبُّ التَّعْزِيَةُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَفْتِنَّ، لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنْ عَزَّى أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. وَالتَّعْزِيَةُ أَنْ يَقُولَ: أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَك، وَأَحْسَنَ عَزَاءَك، وَغَفَرَ لِمَيِّتِك. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبِالْجُلُوسِ لَهَا) أَيْ لِلتَّعْزِيَةِ، وَاسْتِعْمَالُ لَا بَأْسَ هُنَا عَلَى حَقِيقَتِهِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ. وَفِي الْأَحْكَامِ عَنْ خِزَانَةِ الْفَتَاوَى: الْجُلُوسُ فِي الْمُصِيبَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلرِّجَالِ جَاءَتْ الرُّخْصَةُ فِيهِ، وَلَا تَجْلِسُ النِّسَاءُ قَطْعًا اهـ۔۔۔
وَفِي الْإِمْدَادِ: وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ مُتَأَخِّرِي أَئِمَّتِنَا يُكْرَهُ الِاجْتِمَاعُ عِنْدَ صَاحِبِ الْبَيْتِ وَيُكْرَهُ لَهُ الْجُلُوسُ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ إلَيْهِ مَنْ يُعَزِّي، بَلْ إذَا فَرَغَ وَرَجَعَ النَّاسُ مِنْ الدَّفْنِ فَلْيَتَفَرَّقُوا وَيَشْتَغِلُ النَّاسُ بِأُمُورِهِمْ وَصَاحِبُ الْبَيْتِ بِأَمْرِهِ اهـ۔۔۔ (قَوْلُهُ وَتُكْرَهُ التَّعْزِيَةُ ثَانِيًا) فِي التَّتَارْخَانِيَّة: لَا يَنْبَغِي لِمَنْ عَزَّى مَرَّةً أَنْ يُعَزِّيَ مَرَّةً أُخْرَى رَوَاهُ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ. اهـ. إمْدَادٌ۔
تبیین الحقائق مع حاشية الشِّلبیّ(1/246)
[فصل تعزية أهل الميت]
(فصل) ولا بأس بتعزية أهل الميت وترغيبهم في الصبر لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من عزى مصابا فله مثل أجره» ويقول له أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاءك وغفر لميتك ، ولا بأس بالجلوس لها إلى ثلاثة أيام من غير ارتكاب محظور من فرش البسط والأطعمة من أهل الميت ؛ لأنها تتخذ عند السرور۔۔۔
(قوله : لا بأس بتعزية أهل الميت إلخ) ، وأكثرهم على أن يعزى إلى ثلاثة أيام ثم يترك لئلا يتجدد الحزن وروى ابن ماجه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة»۔
فتح الباري لابن حجر - (13 / 253)
والمحدثات بفتح الدال جمع محدثة والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعة وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما وكذا القول في المحدثة وفي الأمر المحدث الذي ورد في حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔۔ و اللہ تعالیٰ اعلم
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
الجواب حامدًا ومصلّياً
۔میت کو دفناکر اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنا اور پہلے ،دوسرےیاتیسرےروزتک ایک مرتبہ تعزیت کرنا مسنون ہے ، تعزیت کے معنی ہیں میت کے متعلقین کو تسلی دینا اور صبر کے فضائل اور اس کا عظیم الشان اجر وثواب سنا کر ان کو صبر کی رغبت دلانا اور میت کے لیے دعاءِمغفرت کرنا خواه كسی بھی زبان میں ہو مثلاً یہ الفاظ کہہ دیے جائیں ’’اللہ تعالی آپ کے ثواب کو بڑھائے اور خوب صبر وتحمل کی توفیق دے اور اللہ مرحوم /مرحومہ کی مغفرت فرمائے ‘‘۔لیکن اس کے لیے ہر آنے والا ہاتھ اٹھاکر تعزیت کرے یا ہاتھ اٹھاکر لازماًدعا کرے یا ہاتھ اٹھا کر تلاوتِ قرآن کرےتویہ طریقہ رسول نبی کریمﷺ،خلفاءراشدین ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ،تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ سے ثابت نہیں،اس لیے تین دن تک بار بار اس عمل کو جاری رکھنا بدعت ہے، جسے چھوڑنا ضروری ہے ۔البتہ اگر کسی وقت تلاوت برائے ایصالِ ثواب کرلی جائےاور بعد میں ہاتھ اٹھاکر میت کے لیے دعا کرلیں تو یہ جائز ہے ،بشرطیکہ ہر آنے والا یہ کام لازماً نہ کرتا ہو۔ جولوگ اس طرح کرتے ہوں ان کو فتنہ اور فساد سے بچتے ہوئےنرمی سے سمجھادیں اور اگر وہ نہ مانیں توخود اس عمل کو برا سمجھتے ہوئے ان کےحق میں ہدایت کی دعا کردیں ۔
مشكاة المصابيح - (1 / 51)
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»
الفتاوى الهندية - (1 / 167)
التعزية لصاحب المصيبة حسن كذا في الظهيرية وروى الحسن بن زياد إذا عزى أهل الميت مرة فلا ينبغي أن يعزيه مرة أخرى كذا في المضمرات ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها إلا أن يكون المعزي أو المعزى إليه غائبا فلا بأس بها وهي بعد الدفن أولى منها قبله وهذا إذا لم ير منهم جزع شديد فإن رئي ذلك قدمت التعزية ويستحب أن يعم بالتعزية جميع أقارب الميت الكبار والصغار والرجال والنساء إلا أن يكون امرأة شابة فلا يعزيها إلا محارمها كذا في السراج الوهاج ويستحب أن يقال لصاحب التعزية غفر الله تعالى لميتك وتجاوز عنه وتغمده برحمته ورزقك الصبر على مصيبته وآجرك على موته كذا في المضمرات ناقلا عن الحجة وأحسن ذلك تعزية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى
============================
بسم اللہ الرحمن الرحیم
الجواب حامدًا ومصلّياً
اہلِ میت کا تعزیت کے لیے مسجد میں بیٹھنااور لوگوں کا مسجد میں آکر تعزیت کرنا مکروہ ہے،خصوصاً جبکہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کی جائیں تو اس کی کراہت میں اور اضافہ ہوجائیگا ۔اسی طرح مروّجہ طریقہ کے مطابق عام گذرگاہ پر شامیانے لگا کر آمد ورفت کا راستہ روک دینا بھی جائز نہیں،کیونکہ اس طرح اس راستہ سے گذرنے والوں کو تکلیف ہوگی،ہاں البتہ اہلِ میت اگر گھر میں ہی رہیں اور لوگ وہاں آکر ان سے تعزیت کریں تو جائز ہے۔(مأخذہ ٗالتبویب:۱۴۵۲/۲۱)
الدر المختار - (2 / 239)
ولا بأس بنقله قبل دفنه۔۔۔ وبالجلوس لها في غير مسجد ثلاثة أيام،
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) - (2 / 241)
(قوله: في غير مسجد) أما فيه فيكره كما في البحر عن المجتبى، وجزم به في شرح المنية والفتح، لكن في الظهيرية: لا بأس به لأهل الميت في البيت أو المسجد والناس يأتونهم ويعزونهم. اهـ. قلت: وما في البحر من «أنه - صلى الله عليه وسلم - جلس لما قتل جعفر وزيد بن حارثة والناس يأتون ويعزونه» اهـ يجاب عنه بأن جلوسه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن مقصودا للتعزية. وفي الإمداد: وقال كثير من متأخري أئمتنا يكره الاجتماع عند صاحب البيت ويكره له الجلوس في بيته حتى يأتي إليه من يعزي، بل إذا فرغ ورجع الناس من الدفن فليتفرقوا ويشتغل الناس بأمورهم وصاحب البيت بأمره اهـ. قلت: وهل تنتفي الكراهة بالجلوس في المسجد وقراءة القرآن حتى إذا فرغوا قام ولي الميت وعزاه الناس كما يفعل في زماننا الظاهر؟ لا لكون الجلوس مقصودا للتعزية لا القراءة ولا سيما إذا كان هذا الاجتماع والجلوس في المقبرة فوق القبور المدثورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله… وما يصنع في بلاد العجم من فرش البسط، والقيام على قوارع الطريق من أقبح القبائح. اهـ.
واللہ اعلم بالصواب
الجواب حامدًا ومصلّياً
۔میت کو دفناکر اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنا اور پہلے ،دوسرےیاتیسرےروزتک ایک مرتبہ تعزیت کرنا مسنون ہے ، تعزیت کے معنی ہیں میت کے متعلقین کو تسلی دینا اور صبر کے فضائل اور اس کا عظیم الشان اجر وثواب سنا کر ان کو صبر کی رغبت دلانا اور میت کے لیے دعاءِمغفرت کرنا خواه كسی بھی زبان میں ہو مثلاً یہ الفاظ کہہ دیے جائیں ’’اللہ تعالی آپ کے ثواب کو بڑھائے اور خوب صبر وتحمل کی توفیق دے اور اللہ مرحوم /مرحومہ کی مغفرت فرمائے ‘‘۔لیکن اس کے لیے ہر آنے والا ہاتھ اٹھاکر تعزیت کرے یا ہاتھ اٹھاکر لازماًدعا کرے یا ہاتھ اٹھا کر تلاوتِ قرآن کرےتویہ طریقہ رسول نبی کریمﷺ،خلفاءراشدین ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ،تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ سے ثابت نہیں،اس لیے تین دن تک بار بار اس عمل کو جاری رکھنا بدعت ہے، جسے چھوڑنا ضروری ہے ۔البتہ اگر کسی وقت تلاوت برائے ایصالِ ثواب کرلی جائےاور بعد میں ہاتھ اٹھاکر میت کے لیے دعا کرلیں تو یہ جائز ہے ،بشرطیکہ ہر آنے والا یہ کام لازماً نہ کرتا ہو۔ جولوگ اس طرح کرتے ہوں ان کو فتنہ اور فساد سے بچتے ہوئےنرمی سے سمجھادیں اور اگر وہ نہ مانیں توخود اس عمل کو برا سمجھتے ہوئے ان کےحق میں ہدایت کی دعا کردیں ۔
مشكاة المصابيح - (1 / 51)
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»
الفتاوى الهندية - (1 / 167)
التعزية لصاحب المصيبة حسن كذا في الظهيرية وروى الحسن بن زياد إذا عزى أهل الميت مرة فلا ينبغي أن يعزيه مرة أخرى كذا في المضمرات ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها إلا أن يكون المعزي أو المعزى إليه غائبا فلا بأس بها وهي بعد الدفن أولى منها قبله وهذا إذا لم ير منهم جزع شديد فإن رئي ذلك قدمت التعزية ويستحب أن يعم بالتعزية جميع أقارب الميت الكبار والصغار والرجال والنساء إلا أن يكون امرأة شابة فلا يعزيها إلا محارمها كذا في السراج الوهاج ويستحب أن يقال لصاحب التعزية غفر الله تعالى لميتك وتجاوز عنه وتغمده برحمته ورزقك الصبر على مصيبته وآجرك على موته كذا في المضمرات ناقلا عن الحجة وأحسن ذلك تعزية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى
============================
بسم اللہ الرحمن الرحیم
الجواب حامدًا ومصلّياً
اہلِ میت کا تعزیت کے لیے مسجد میں بیٹھنااور لوگوں کا مسجد میں آکر تعزیت کرنا مکروہ ہے،خصوصاً جبکہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کی جائیں تو اس کی کراہت میں اور اضافہ ہوجائیگا ۔اسی طرح مروّجہ طریقہ کے مطابق عام گذرگاہ پر شامیانے لگا کر آمد ورفت کا راستہ روک دینا بھی جائز نہیں،کیونکہ اس طرح اس راستہ سے گذرنے والوں کو تکلیف ہوگی،ہاں البتہ اہلِ میت اگر گھر میں ہی رہیں اور لوگ وہاں آکر ان سے تعزیت کریں تو جائز ہے۔(مأخذہ ٗالتبویب:۱۴۵۲/۲۱)
الدر المختار - (2 / 239)
ولا بأس بنقله قبل دفنه۔۔۔ وبالجلوس لها في غير مسجد ثلاثة أيام،
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) - (2 / 241)
(قوله: في غير مسجد) أما فيه فيكره كما في البحر عن المجتبى، وجزم به في شرح المنية والفتح، لكن في الظهيرية: لا بأس به لأهل الميت في البيت أو المسجد والناس يأتونهم ويعزونهم. اهـ. قلت: وما في البحر من «أنه - صلى الله عليه وسلم - جلس لما قتل جعفر وزيد بن حارثة والناس يأتون ويعزونه» اهـ يجاب عنه بأن جلوسه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن مقصودا للتعزية. وفي الإمداد: وقال كثير من متأخري أئمتنا يكره الاجتماع عند صاحب البيت ويكره له الجلوس في بيته حتى يأتي إليه من يعزي، بل إذا فرغ ورجع الناس من الدفن فليتفرقوا ويشتغل الناس بأمورهم وصاحب البيت بأمره اهـ. قلت: وهل تنتفي الكراهة بالجلوس في المسجد وقراءة القرآن حتى إذا فرغوا قام ولي الميت وعزاه الناس كما يفعل في زماننا الظاهر؟ لا لكون الجلوس مقصودا للتعزية لا القراءة ولا سيما إذا كان هذا الاجتماع والجلوس في المقبرة فوق القبور المدثورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله… وما يصنع في بلاد العجم من فرش البسط، والقيام على قوارع الطريق من أقبح القبائح. اهـ.
واللہ اعلم بالصواب
*جبراً طلاق نامہ پر دستخط*
سوال:- میرے شوہر کی عمر ۵۵ سال اور میری عمر ۴۷ سال ہے ، دو بیٹیاں شادی شدہ ہیں ، چار نواسے نواسیاں ہیں ، بیٹا بھی ماشاء اللہ شادی کے قابل ہے ، ہم دونوں میاں بیوی میں معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا اور بحث و تکرار کے بعد میں بضد تھی کہ وہ مجھے طلاق دیں ؛ لیکن میرے شوہر اس کے لئے بالکل ہی تیار نہیں تھے ، بیوی نے اپنے ہاتھ سے تحریر لکھی کہ میں تمہیں تین طلاق دیتا ہوں ، اور ان سے دستخط کرنے کے لئے کہا ؛ لیکن شوہر ہرگز تیار نہیں تھے ، دستخط کرنے کے لئے ، لیکن میں نے بہت زور ڈالا ، اس کے باوجود بھی وہ تیار نہیں تھے ، آخر کار میں گلے میں دوپٹہ پھنساکر ان سے زبردستی دستخط کے لئے کہا ، انھوںنے ڈر و خوف کے مارے دستخط کردیئے ، اب میرے شوہر کا یہ کہنا ہے کہ وہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتے ہیں کہ میرے دل سے ہرگز طلاق دینے کا نہیں تھا ، محض تمہاری جان بچانے کے لئے ایسا کیا ، مقامی مفتیوں نے بھی کہا کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوئی ؛ لیکن میرا ضمیر مطمئن نہیں ، مہربانی فرماکر آپ اس مسئلہ کا شرعی حل بتائیں ۔ (امۃ اللہ ، حیدرآباد)
بسم اللہ الرحمن الرحیم
الجواب حامداًومصلیاً
اول تو یہ بات یاد رکھئے کہ جیسے مرد کے لئے کسی مناسب سبب کے بغیر طلاق دینا گناہ ہے ، اسی طرح عورت کے لئے کسی معقول وجہ کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرنا سخت منع ہے ، رسول اللہ انے ایسی عورتوں کے بارے میں جو اس طرح طلاق کا مطالبہ کرے ، فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی :’’ أیما امرأۃ اختلعت من زوجھا من غیر بأس لم ترح رائحۃ الجنۃ ‘‘ ( ترمذی ، باب ماجاء فی المختلعات ، حدیث نمبر : ۱۱۸۶) اس لئے معمولی سے جھگڑے کی بناپر طلاق کا مطالبہ گناہ کی بات ہے اور جب خاندان کی عمر دراز عورتیں اس طرح کی حرکتیں کریں گی تو بیٹیوں اور بہوؤں پر بھی اس کا اثر پڑے گا ؛ اس لئے طے کرلیجئے کہ پھر آئندہ طلاق و خلع کا لفظ اپنی زبان پر نہ لائیں گے — شوہر کے طلاق نامہ پر دستخط کرنے کی دو صورتیں ہیں : ایک یہ کہ بیوی سامنے موجود تھی ؛ لیکن اس نے صرف دستخط کیا ، زبان سے کچھ نہیں کہا ، تو اس صورت میں شوہر کو مجبور کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو ، طلاق واقع نہیں ہوگی ؛ کیوںکہ جب بیوی موجود ہو اور زبان سے طلاق دی جاسکتی ہو تو صرف لکھ دینے سے طلاق واقع نہیں ہوگی ، اور اگر بیوی سامنے موجود نہ ہو اور شوہر کو طلاق لکھنے یا دستخط کرنے پر مجبور کردیا گیا ہو ؛ لیکن زبان سے اس نے طلاق کے الفاظ نہیں کہے ، تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی ، دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر نے زبان سے طلاق کے کلمات کہے تو چاہے مجبوری کی وجہ سے طلاق کے کلمات کہے ہوں یا بغیر مجبوری کے ، ہر دو صورت میں طلاق واقع ہوجائے گی : ’’ وقید بکونہ علی النطق لأنہ لو أکرہ علی أن یکتب طلاق امرأتہ ، فکتب لا تطلق لأن الکتابۃ اقیمت مقام العبارۃ باعتبار الحاجۃ ولا حاجۃ ھنا ، کذا فی الخانیۃ ‘‘ (البحر الرائق ، کتاب الطلاق : ۳؍۲۶۴) بہر حال آپ نے جو صورت لکھی ہے ، اس کے مطابق شوہر کے طلاق نامہ پر دستخط کرنے کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوئی ؛ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انھیں طلاق پر مجبور بھی کیا گیا ، اس لئے بدرجۂ اولیٰ طلاق واقع نہیں ہوگی .
*حضرت مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب*.
http://www.baseeratonline.com/52533.php
سوال:- میرے شوہر کی عمر ۵۵ سال اور میری عمر ۴۷ سال ہے ، دو بیٹیاں شادی شدہ ہیں ، چار نواسے نواسیاں ہیں ، بیٹا بھی ماشاء اللہ شادی کے قابل ہے ، ہم دونوں میاں بیوی میں معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا اور بحث و تکرار کے بعد میں بضد تھی کہ وہ مجھے طلاق دیں ؛ لیکن میرے شوہر اس کے لئے بالکل ہی تیار نہیں تھے ، بیوی نے اپنے ہاتھ سے تحریر لکھی کہ میں تمہیں تین طلاق دیتا ہوں ، اور ان سے دستخط کرنے کے لئے کہا ؛ لیکن شوہر ہرگز تیار نہیں تھے ، دستخط کرنے کے لئے ، لیکن میں نے بہت زور ڈالا ، اس کے باوجود بھی وہ تیار نہیں تھے ، آخر کار میں گلے میں دوپٹہ پھنساکر ان سے زبردستی دستخط کے لئے کہا ، انھوںنے ڈر و خوف کے مارے دستخط کردیئے ، اب میرے شوہر کا یہ کہنا ہے کہ وہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتے ہیں کہ میرے دل سے ہرگز طلاق دینے کا نہیں تھا ، محض تمہاری جان بچانے کے لئے ایسا کیا ، مقامی مفتیوں نے بھی کہا کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوئی ؛ لیکن میرا ضمیر مطمئن نہیں ، مہربانی فرماکر آپ اس مسئلہ کا شرعی حل بتائیں ۔ (امۃ اللہ ، حیدرآباد)
بسم اللہ الرحمن الرحیم
الجواب حامداًومصلیاً
اول تو یہ بات یاد رکھئے کہ جیسے مرد کے لئے کسی مناسب سبب کے بغیر طلاق دینا گناہ ہے ، اسی طرح عورت کے لئے کسی معقول وجہ کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرنا سخت منع ہے ، رسول اللہ انے ایسی عورتوں کے بارے میں جو اس طرح طلاق کا مطالبہ کرے ، فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی :’’ أیما امرأۃ اختلعت من زوجھا من غیر بأس لم ترح رائحۃ الجنۃ ‘‘ ( ترمذی ، باب ماجاء فی المختلعات ، حدیث نمبر : ۱۱۸۶) اس لئے معمولی سے جھگڑے کی بناپر طلاق کا مطالبہ گناہ کی بات ہے اور جب خاندان کی عمر دراز عورتیں اس طرح کی حرکتیں کریں گی تو بیٹیوں اور بہوؤں پر بھی اس کا اثر پڑے گا ؛ اس لئے طے کرلیجئے کہ پھر آئندہ طلاق و خلع کا لفظ اپنی زبان پر نہ لائیں گے — شوہر کے طلاق نامہ پر دستخط کرنے کی دو صورتیں ہیں : ایک یہ کہ بیوی سامنے موجود تھی ؛ لیکن اس نے صرف دستخط کیا ، زبان سے کچھ نہیں کہا ، تو اس صورت میں شوہر کو مجبور کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو ، طلاق واقع نہیں ہوگی ؛ کیوںکہ جب بیوی موجود ہو اور زبان سے طلاق دی جاسکتی ہو تو صرف لکھ دینے سے طلاق واقع نہیں ہوگی ، اور اگر بیوی سامنے موجود نہ ہو اور شوہر کو طلاق لکھنے یا دستخط کرنے پر مجبور کردیا گیا ہو ؛ لیکن زبان سے اس نے طلاق کے الفاظ نہیں کہے ، تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی ، دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر نے زبان سے طلاق کے کلمات کہے تو چاہے مجبوری کی وجہ سے طلاق کے کلمات کہے ہوں یا بغیر مجبوری کے ، ہر دو صورت میں طلاق واقع ہوجائے گی : ’’ وقید بکونہ علی النطق لأنہ لو أکرہ علی أن یکتب طلاق امرأتہ ، فکتب لا تطلق لأن الکتابۃ اقیمت مقام العبارۃ باعتبار الحاجۃ ولا حاجۃ ھنا ، کذا فی الخانیۃ ‘‘ (البحر الرائق ، کتاب الطلاق : ۳؍۲۶۴) بہر حال آپ نے جو صورت لکھی ہے ، اس کے مطابق شوہر کے طلاق نامہ پر دستخط کرنے کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوئی ؛ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انھیں طلاق پر مجبور بھی کیا گیا ، اس لئے بدرجۂ اولیٰ طلاق واقع نہیں ہوگی .
*حضرت مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب*.
http://www.baseeratonline.com/52533.php
# فقہیات #
*بیوی کا اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا*
سوشل میڈیا پر یہ بحث اکثر موضوع سخن بنتی ہے کہ بیوی کا اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھنا یا لگانا حرام ہے، لیکن یہ بات قطعی طور پر درست نہیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں ممانعت اس بات کی ہے جہاں آدمی اپنی ولدیت اور نسب کو تبدیل کردے، یعنی اپنے حقیقی والد کو چھوڑ کر دوسرے شخص کو اپنا والد ظاہر کرے یا اپنا سلسلہ نسب کسی اور فرد سے جوڑے، اگر کوئی بطور تعارف کے اپنے نام کے ساتھ کوئی نسبت یا تخلص لگاتا ہے اور معاشرے میں اس کو اس کی ولدیت نہیں سمجھا جاتا تو یہ لگانا جائز ہے، اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے:
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب : 4 ، 5]
یعنی اللہ تعالی نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا، یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو، اور اللہ وہی بات کہتا ہے جو حق ہو، اور وہی صحیح راستہ بتلاتا ہے،تم ان (منہ بولے بیٹوں) کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا ہے اور اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں۔
● حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جانتے ہوئے (اپنے باپ کو چھوڑ کر) کسی دوسرے کو اپنا باپ ظاہر کیا، اس پر جنت حرام ہے۔ (رواہ الشیخان فی الصحیحین واحمد وابو داؤد و ابن ماجة)
● ایک دوسری روایت میں ارشاد گرامی ہے کہ جس نے (اپنے باپ کو چھوڑ کر) کسی دوسرے کو اپنا باپ بتایا، یا کسی (آزاد کردہ غلام) نے اپنے مولیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف اپنا مولیٰ ہونے کی نسبت کی، اس پر قیامت کے دن تک اللہ کی مسلسل لعنت ہوگی۔ (رواہ ابو داؤد، سیوطی نے کہا : یہ حدیث صحیح ہے۔)
چنانچہ لے پالک کے بارے میں یہ نصوص واضح ہیں کہ ان کو ان کے حقیقی والد کی طرف منسوب کیا جائے، اور چونکہ پرورش کرنے والا حقیقی باپ کے درجے میں نہیں ہوتا، لہذا اُس کا اپنے آپ کو اس کے والد کے طور پر پکارنا اور کاغذات میں لکھوانا جائز نہیں، جبکہ کسی لڑکی کا شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگانا اس لئے نہیں ہوتا کہ وہ اپنا والد یا نسب تبدیل کررہی ہوتی ہے بلکہ یہ صرف تعارف کے لئے ہوتا ہے، اور یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنا نسب تبدیل کررہی ہے، ہمارے معاشرے میں عام طور پر لڑکی کی شادی سے پہلے والد کا نام لکھا جاتا ہے جو کہ اثبات ِ نسب ہے اور یہ شریعت کے عین مطابق ہے، تاہم شادی کے بعد شوہر کا نام لکھنا بطور تعارف کے ہے جس کی بسا اوقات بعض قانونی وجوہات کے طور پر ضرورت پیش آتی ہے جو کہ شرعا جائز ہے، تاہم اگر کسی عورت کیلئے اپنے شوہر کا نام لکھنے میں نسب کے مشتبہ ہونے کا اندیشہ ہو اور لوگ اس کے شوہر کو اس کا والد سمجھنے لگیں تو اس عورت کیلئے اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لکھنا درست نہ ہوگا۔
یہ واضح رہے کہ کسی کے نام کے ساتھ اس کے کسی تعارف کا ہونا فطری امر ہے اور یہ انسان کا معاشرہ میں مختلف نسبتوں سے تعارف نعمت خداوندی ہے جس کا سورة الحجرات میں بھی ذکر ہے اور اس سے اختلاطِ نسب کا وہم نہیں ہوتا، پھر تعارف کا باب بہت وسیع ہے، تعارف کبھی ولاء سے ہوتا ہے جیسے عکرمہ مولی ابن عباس، کبھی حرفت سے ہوتا ہے جیسے قدروری و غزالی،کبھی لقب اور کنیت سے ہوتا ہے جیسے أعرج اور ابو محمد أعمش، کبھی ماں کی طرف نسبت کرکے ہوتا ہے حالانکہ باپ معروف ہوتا ہے جیسے عبد اللہ ابن ام مکتوم، اسماعیل ابن علیة اور کبھی زوجیت کے ساتھ ہوتا ہےجیسا قرآن مجید میں ایک جگہ"امرأۃ نوح وامرأۃ لوط" ( التحریم:۱۰) اور دوسری جگہ "امرأۃ فرعون" ( التحریم:۱۱) وارد ہے۔
صحیحین میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:
جَاءَتْ زَيْنَبُ، امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ زَيْنَبُ، فَقَالَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟» فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «نَعَمْ، ائْذَنُوا لَهَا» (بخاری :۱٤٦٢)
حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب آئیں اور اجازت طلب کی، اور کہا گیا کہ یا رسول اللہ ! یہ زینب آئی ہیں، آپ نے پوچھا کہ کونسی زینب؟ بتایا گیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی! فرمایا کہ ہاں اسے آنے کی اجازت دے دو۔
یاد رہے کہ نسبت وہ حرام ہے جس میں ولدیت کے لفظ کے ساتھ والد کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی جائے، مطلقاً نسبت یا تعریف کے لئے نسبت کرنا حرام نہیں ہے۔
ولو کنی إبنه الصغیر بأبي بکرا وغیرہ الصحیح أنه لابأس به، فإن الناس یریدون التفاؤل أنه یصیر أبا في ثاني الحال لا التحقیق في الحال۔ (ہندیۃ، الباب الثاني والعشرون
*بیوی کا اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا*
سوشل میڈیا پر یہ بحث اکثر موضوع سخن بنتی ہے کہ بیوی کا اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھنا یا لگانا حرام ہے، لیکن یہ بات قطعی طور پر درست نہیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں ممانعت اس بات کی ہے جہاں آدمی اپنی ولدیت اور نسب کو تبدیل کردے، یعنی اپنے حقیقی والد کو چھوڑ کر دوسرے شخص کو اپنا والد ظاہر کرے یا اپنا سلسلہ نسب کسی اور فرد سے جوڑے، اگر کوئی بطور تعارف کے اپنے نام کے ساتھ کوئی نسبت یا تخلص لگاتا ہے اور معاشرے میں اس کو اس کی ولدیت نہیں سمجھا جاتا تو یہ لگانا جائز ہے، اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے:
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب : 4 ، 5]
یعنی اللہ تعالی نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا، یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو، اور اللہ وہی بات کہتا ہے جو حق ہو، اور وہی صحیح راستہ بتلاتا ہے،تم ان (منہ بولے بیٹوں) کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا ہے اور اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں۔
● حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جانتے ہوئے (اپنے باپ کو چھوڑ کر) کسی دوسرے کو اپنا باپ ظاہر کیا، اس پر جنت حرام ہے۔ (رواہ الشیخان فی الصحیحین واحمد وابو داؤد و ابن ماجة)
● ایک دوسری روایت میں ارشاد گرامی ہے کہ جس نے (اپنے باپ کو چھوڑ کر) کسی دوسرے کو اپنا باپ بتایا، یا کسی (آزاد کردہ غلام) نے اپنے مولیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف اپنا مولیٰ ہونے کی نسبت کی، اس پر قیامت کے دن تک اللہ کی مسلسل لعنت ہوگی۔ (رواہ ابو داؤد، سیوطی نے کہا : یہ حدیث صحیح ہے۔)
چنانچہ لے پالک کے بارے میں یہ نصوص واضح ہیں کہ ان کو ان کے حقیقی والد کی طرف منسوب کیا جائے، اور چونکہ پرورش کرنے والا حقیقی باپ کے درجے میں نہیں ہوتا، لہذا اُس کا اپنے آپ کو اس کے والد کے طور پر پکارنا اور کاغذات میں لکھوانا جائز نہیں، جبکہ کسی لڑکی کا شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگانا اس لئے نہیں ہوتا کہ وہ اپنا والد یا نسب تبدیل کررہی ہوتی ہے بلکہ یہ صرف تعارف کے لئے ہوتا ہے، اور یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنا نسب تبدیل کررہی ہے، ہمارے معاشرے میں عام طور پر لڑکی کی شادی سے پہلے والد کا نام لکھا جاتا ہے جو کہ اثبات ِ نسب ہے اور یہ شریعت کے عین مطابق ہے، تاہم شادی کے بعد شوہر کا نام لکھنا بطور تعارف کے ہے جس کی بسا اوقات بعض قانونی وجوہات کے طور پر ضرورت پیش آتی ہے جو کہ شرعا جائز ہے، تاہم اگر کسی عورت کیلئے اپنے شوہر کا نام لکھنے میں نسب کے مشتبہ ہونے کا اندیشہ ہو اور لوگ اس کے شوہر کو اس کا والد سمجھنے لگیں تو اس عورت کیلئے اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لکھنا درست نہ ہوگا۔
یہ واضح رہے کہ کسی کے نام کے ساتھ اس کے کسی تعارف کا ہونا فطری امر ہے اور یہ انسان کا معاشرہ میں مختلف نسبتوں سے تعارف نعمت خداوندی ہے جس کا سورة الحجرات میں بھی ذکر ہے اور اس سے اختلاطِ نسب کا وہم نہیں ہوتا، پھر تعارف کا باب بہت وسیع ہے، تعارف کبھی ولاء سے ہوتا ہے جیسے عکرمہ مولی ابن عباس، کبھی حرفت سے ہوتا ہے جیسے قدروری و غزالی،کبھی لقب اور کنیت سے ہوتا ہے جیسے أعرج اور ابو محمد أعمش، کبھی ماں کی طرف نسبت کرکے ہوتا ہے حالانکہ باپ معروف ہوتا ہے جیسے عبد اللہ ابن ام مکتوم، اسماعیل ابن علیة اور کبھی زوجیت کے ساتھ ہوتا ہےجیسا قرآن مجید میں ایک جگہ"امرأۃ نوح وامرأۃ لوط" ( التحریم:۱۰) اور دوسری جگہ "امرأۃ فرعون" ( التحریم:۱۱) وارد ہے۔
صحیحین میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:
جَاءَتْ زَيْنَبُ، امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ زَيْنَبُ، فَقَالَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟» فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «نَعَمْ، ائْذَنُوا لَهَا» (بخاری :۱٤٦٢)
حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب آئیں اور اجازت طلب کی، اور کہا گیا کہ یا رسول اللہ ! یہ زینب آئی ہیں، آپ نے پوچھا کہ کونسی زینب؟ بتایا گیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی! فرمایا کہ ہاں اسے آنے کی اجازت دے دو۔
یاد رہے کہ نسبت وہ حرام ہے جس میں ولدیت کے لفظ کے ساتھ والد کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی جائے، مطلقاً نسبت یا تعریف کے لئے نسبت کرنا حرام نہیں ہے۔
ولو کنی إبنه الصغیر بأبي بکرا وغیرہ الصحیح أنه لابأس به، فإن الناس یریدون التفاؤل أنه یصیر أبا في ثاني الحال لا التحقیق في الحال۔ (ہندیۃ، الباب الثاني والعشرون
في شمیۃ الأولاد، زکریا قدیم ۵/ ۳٦٢، جدید ۵/ ٤١٨، المحیط البرہاني، المجلس العلمي بیروت ۸/ ۹٦، رقم: ۹٦٧٨، الموسوعة الفقہیة الکویتیة ۳۵/ ۱۷۱، الفتاوی التارتارخانیة زکریا ۱۸/ ۲۲۹، رقم: ۲۸٦٠٦)
*ناشر: دارالریان کراتشی*
*ناشر: دارالریان کراتشی*
بسم اللہ الرحمن الرحیم
الجواب حامدًا ومصلّياً
*یہاں ہر چند مزید ممکنہ صورتیں پیداہوسکتی ہیں۔ جن کی طرف سائل نے توجہ نہیں دی۔ لہذا فائدے کے طور پر ان صورتوں کا حکم بھی اجمالاً بیان کردینا ضروری معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ ٹیسٹ ٹیوب بے بی کے ذریعہ اولاد حاصل کرنے کا تیسرا طریقہ یہ بھی ہوسکتا ہے۔*
(الف) کہ کوئی شخص نکاح کئے بغیر اولاد حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہ کسی عورت کو اولاد حاصل کرنے واسطے کرائے پر لے اور اس سے فطری طریقہ سے زنا کرے یا غیر فطری طریقہ سے ٹیسٹ ٹیوب بے بی کے نظام سے اپنے جرثومے کو اس کے رحم میں داخل کرکے اولاد حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کا حکم بھی زنا کا ہے او راس سے ہونے والابچہ بھی ولد الزنا ہے۔
(ب) چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اولاد حاصل کرنے کی سعی کرنے والا مرد نہ ہو بلکہ کوئی عورت ہو کہ وہ بلا نکاح کسی مرد کو کرائے پر لے کر اس سے اس طریقہ سے زنا کرکے بچہ پیدا کرے یا کسی اجنبی مرد کے مادہ منویہ کو غیر فطری طریقے سے اپنے رحم میں داخل کرکے بچہ پیدا کرے، یہ بھی زنا کے حکم میں ہے۔ اس میں بچہ تو عورت کو مل جائے گا، لیکن اس کو ولد الزنا کہا جائے گا۔ اس طرح بچہ حاصل کرنا شرعاً جائز نہ ہوگا۔
(ج) پانچواں طریقہ یہ ہے کہ اولاد حاصل کرنے کے خواہشمند میاں بیوی ہوں لیکن ان کے جرثومے ناقص یا اولاد پیدا کرنے والے نہ ہونے کی بناء پر کسی ایسے اجنبی مرد کے جرثومے کو ملا کر بیوی کے رحم میں داخل کردیں جس کے جرثومے میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہو یا میاں بیوی دونوں کے جرثومے کسی اجنبی عورت کے رحم میں داخل کردیں۔
*ان صورتوں میں خلط نسب کے شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تاہم جس عورت کے بطن اور حمل سے بچہ پید اہوگا، بچہ کی نسبت اس کی طرف ہوگی اور وہ اگر شوہر والی عورت ہے تو اس کے شوہر سے بچہ کا نسب ہوگا۔*
خواہشمند عورت سے نہ ہوگا اور اگرعورت بے شوہر ہے تو صرف اسی عورت سے نسب ثابت ہوگا، جس کے بطن میں حمل ٹھہرا ہو اور جس عورت کو اولاد کی خواہش تھی اور اس کے جرثومے بھی ملائے گئے ہوں، اس سے نسب کا ثبوت نہ ہوگا۔
بہرحال اس میں مزید صورتیں پیدا ہوسکتی ہیں۔ لیکن ہم نے جو اصول بیان کردیئے ہیں اور جس تفصیل سے اصول اور مسائل کو دلائل سے ذکر کیا ہے، اس سے مزید پید اہونے والے مسائل کا حل بھی انشاء اللہ ملے گا۔ ایک ادنیٰ درجہ کی عقل رکھنے والے کی بصیرت و علم کے لئے اتنا کافی ہے۔
’’مشورہ ‘‘۔
واضح رہے کہ جس مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوت مردانیت کی صفت سے نوازا ہے، اگر اس کی بیوی کے اندر کسی کمی کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی تو وہ دوسری، تیسری، چوتھی شادی کرکے اولاد کی خواہش پوری کرسکتا ہے۔ اس طرح مرد اور عورت دونوں اولاد سے مالا مال ہوسکتے ہیں۔ کسی غیر شرعی فعل کا ارتکاب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور اگر مرد کے اندر مردانیت نہیں ہے، یا کوئی خامی ہے اور عورت کا حال درست ہے تو ایسے موقع پر مرد کو چاہئے کہ ممکنہ علاج کرکے اپنی قوت مردانیت کو بحال کرنے کی کوشش کرے
اور اگر علاج بالکل مفید نہ ہو تو ایسے حالات میں عورت کے فطری جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے اسے طلاق دے دے اور اس کے فطری جذبات کو قربان نہ کرے۔ ایسے موقع پر طلاق نہ دینا گناہ ہے۔ یہ چند کلمات لکھ دیئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے اور لوگوں کے لئے نافع اور سبب موعظت بنادے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والصلوٰۃ والسلام علی سید المرسلین والہ واصحابہ اجمعین
کتبہ : محمد عبدالسلام عفا اﷲ عنہ
بینات -ذو الحجہ /محرم الحرام /صفر۱۴۰۸-۱۴۰۹ھ
بمطابق اگست/ستمبر۱۹۸۸ء
جلد: ۵۰- شمارہ- ۱۲-۱-۲
الجواب حامدًا ومصلّياً
*یہاں ہر چند مزید ممکنہ صورتیں پیداہوسکتی ہیں۔ جن کی طرف سائل نے توجہ نہیں دی۔ لہذا فائدے کے طور پر ان صورتوں کا حکم بھی اجمالاً بیان کردینا ضروری معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ ٹیسٹ ٹیوب بے بی کے ذریعہ اولاد حاصل کرنے کا تیسرا طریقہ یہ بھی ہوسکتا ہے۔*
(الف) کہ کوئی شخص نکاح کئے بغیر اولاد حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہ کسی عورت کو اولاد حاصل کرنے واسطے کرائے پر لے اور اس سے فطری طریقہ سے زنا کرے یا غیر فطری طریقہ سے ٹیسٹ ٹیوب بے بی کے نظام سے اپنے جرثومے کو اس کے رحم میں داخل کرکے اولاد حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کا حکم بھی زنا کا ہے او راس سے ہونے والابچہ بھی ولد الزنا ہے۔
(ب) چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اولاد حاصل کرنے کی سعی کرنے والا مرد نہ ہو بلکہ کوئی عورت ہو کہ وہ بلا نکاح کسی مرد کو کرائے پر لے کر اس سے اس طریقہ سے زنا کرکے بچہ پیدا کرے یا کسی اجنبی مرد کے مادہ منویہ کو غیر فطری طریقے سے اپنے رحم میں داخل کرکے بچہ پیدا کرے، یہ بھی زنا کے حکم میں ہے۔ اس میں بچہ تو عورت کو مل جائے گا، لیکن اس کو ولد الزنا کہا جائے گا۔ اس طرح بچہ حاصل کرنا شرعاً جائز نہ ہوگا۔
(ج) پانچواں طریقہ یہ ہے کہ اولاد حاصل کرنے کے خواہشمند میاں بیوی ہوں لیکن ان کے جرثومے ناقص یا اولاد پیدا کرنے والے نہ ہونے کی بناء پر کسی ایسے اجنبی مرد کے جرثومے کو ملا کر بیوی کے رحم میں داخل کردیں جس کے جرثومے میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہو یا میاں بیوی دونوں کے جرثومے کسی اجنبی عورت کے رحم میں داخل کردیں۔
*ان صورتوں میں خلط نسب کے شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تاہم جس عورت کے بطن اور حمل سے بچہ پید اہوگا، بچہ کی نسبت اس کی طرف ہوگی اور وہ اگر شوہر والی عورت ہے تو اس کے شوہر سے بچہ کا نسب ہوگا۔*
خواہشمند عورت سے نہ ہوگا اور اگرعورت بے شوہر ہے تو صرف اسی عورت سے نسب ثابت ہوگا، جس کے بطن میں حمل ٹھہرا ہو اور جس عورت کو اولاد کی خواہش تھی اور اس کے جرثومے بھی ملائے گئے ہوں، اس سے نسب کا ثبوت نہ ہوگا۔
بہرحال اس میں مزید صورتیں پیدا ہوسکتی ہیں۔ لیکن ہم نے جو اصول بیان کردیئے ہیں اور جس تفصیل سے اصول اور مسائل کو دلائل سے ذکر کیا ہے، اس سے مزید پید اہونے والے مسائل کا حل بھی انشاء اللہ ملے گا۔ ایک ادنیٰ درجہ کی عقل رکھنے والے کی بصیرت و علم کے لئے اتنا کافی ہے۔
’’مشورہ ‘‘۔
واضح رہے کہ جس مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوت مردانیت کی صفت سے نوازا ہے، اگر اس کی بیوی کے اندر کسی کمی کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی تو وہ دوسری، تیسری، چوتھی شادی کرکے اولاد کی خواہش پوری کرسکتا ہے۔ اس طرح مرد اور عورت دونوں اولاد سے مالا مال ہوسکتے ہیں۔ کسی غیر شرعی فعل کا ارتکاب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور اگر مرد کے اندر مردانیت نہیں ہے، یا کوئی خامی ہے اور عورت کا حال درست ہے تو ایسے موقع پر مرد کو چاہئے کہ ممکنہ علاج کرکے اپنی قوت مردانیت کو بحال کرنے کی کوشش کرے
اور اگر علاج بالکل مفید نہ ہو تو ایسے حالات میں عورت کے فطری جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے اسے طلاق دے دے اور اس کے فطری جذبات کو قربان نہ کرے۔ ایسے موقع پر طلاق نہ دینا گناہ ہے۔ یہ چند کلمات لکھ دیئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے اور لوگوں کے لئے نافع اور سبب موعظت بنادے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والصلوٰۃ والسلام علی سید المرسلین والہ واصحابہ اجمعین
کتبہ : محمد عبدالسلام عفا اﷲ عنہ
بینات -ذو الحجہ /محرم الحرام /صفر۱۴۰۸-۱۴۰۹ھ
بمطابق اگست/ستمبر۱۹۸۸ء
جلد: ۵۰- شمارہ- ۱۲-۱-۲
*ادھیا پردینا*
سوال:- بکریوں کو ادھیا پردیتے ہیں یعنی بکری دے دی ،جب بچہ پیدا ہوا تو اگر دو ہوئے ،توایک لے لیا، اورایک ہواتوآد ھا لے لیا، یہ طریقہ جائزہے یانہیں،اگرناجائز ہو تو جو طریقہ ادھیا پردینے کا جائز ہووہ بتلادیں ؟
*الجوا ب حامداًومصلیاً*
یہ طریقہ درست نہیں ہے ، البتہ نصف بکری فروخت کردیں اورقیمت معاف کردیں ، تو وہ نصف کا شریک ہوجائے گا، نصف بکری اس کی ہوگی اوردودھ بکری بچے سب نصفا نصفی ہوں گے ۔۱
فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم
حررہ العبدمحمودغفرلہٗ دارالعلوم دیوبند
_______________________
*ادھیا پرجانور دینا*
سوال:- اُدھار جانوردینا جائز ہے یانہیں، یعنی جانور میرا اور خدمت آپ کی ، پھر وہ جانورمدت مقررہ پر سال دو سال میں پہنچے گا ،توپھر ثالث شخص اس جانور کی قیمت ڈال دیتا ہے ، فریقین میں جس کا دل چاہتاہے ، جانور رکھ لیتاہے ، اورجس کا دل چاہتاہے ، قیمت لے لیتا ہے ، کیا یہ صورت جائز ہے یانہیں؟ اورجواز کی کونسی صورت ہے ؟
*الجواب حامداًومصلیاً*
یہ صورت اجارۂ فاسدہ ہے جو کہ ناجائز ہے ،جواز کی صورت یہ ہے کہ جانور کی قیمت
لگاکرنصف حصہ فروخت کردے ،اب دوسرا شخص اس نصف کو خریدے، پھرجانور والا اس نصف قیمت کو معاف کردے ،اب اس جانور میں دونوں برابر کے شریک ہیں، اس کی کل منفعت دودھ ،بچے وغیرہ بھی مشترک ہیں،اگر فروخت کردیں ، توقیمت بھی نصفا نصف ہوگی، فتاویٰ عالمگیر میں یہ صورت بطور حیلہ ٔ جواز لکھی ہے ۔
*فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم حررہ العبد محمودغفرلہٗ معین مفتی مدرسہ مظاہرعلوم سہارنپور ۲۴؍ربیع الثانی ۶۴ھ*
*الجواب صحیح: عبداللطیف غفرلہٗ مفتی مدرسہ مظاہرعلوم سہارنپور ۲۴؍ربیع الثانی ۶۴ھ*
======================
واللہ اعلم بالصواب
محمد مصروف مظاہری
@anwarulfuqaha
سوال:- بکریوں کو ادھیا پردیتے ہیں یعنی بکری دے دی ،جب بچہ پیدا ہوا تو اگر دو ہوئے ،توایک لے لیا، اورایک ہواتوآد ھا لے لیا، یہ طریقہ جائزہے یانہیں،اگرناجائز ہو تو جو طریقہ ادھیا پردینے کا جائز ہووہ بتلادیں ؟
*الجوا ب حامداًومصلیاً*
یہ طریقہ درست نہیں ہے ، البتہ نصف بکری فروخت کردیں اورقیمت معاف کردیں ، تو وہ نصف کا شریک ہوجائے گا، نصف بکری اس کی ہوگی اوردودھ بکری بچے سب نصفا نصفی ہوں گے ۔۱
فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم
حررہ العبدمحمودغفرلہٗ دارالعلوم دیوبند
_______________________
*ادھیا پرجانور دینا*
سوال:- اُدھار جانوردینا جائز ہے یانہیں، یعنی جانور میرا اور خدمت آپ کی ، پھر وہ جانورمدت مقررہ پر سال دو سال میں پہنچے گا ،توپھر ثالث شخص اس جانور کی قیمت ڈال دیتا ہے ، فریقین میں جس کا دل چاہتاہے ، جانور رکھ لیتاہے ، اورجس کا دل چاہتاہے ، قیمت لے لیتا ہے ، کیا یہ صورت جائز ہے یانہیں؟ اورجواز کی کونسی صورت ہے ؟
*الجواب حامداًومصلیاً*
یہ صورت اجارۂ فاسدہ ہے جو کہ ناجائز ہے ،جواز کی صورت یہ ہے کہ جانور کی قیمت
لگاکرنصف حصہ فروخت کردے ،اب دوسرا شخص اس نصف کو خریدے، پھرجانور والا اس نصف قیمت کو معاف کردے ،اب اس جانور میں دونوں برابر کے شریک ہیں، اس کی کل منفعت دودھ ،بچے وغیرہ بھی مشترک ہیں،اگر فروخت کردیں ، توقیمت بھی نصفا نصف ہوگی، فتاویٰ عالمگیر میں یہ صورت بطور حیلہ ٔ جواز لکھی ہے ۔
*فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم حررہ العبد محمودغفرلہٗ معین مفتی مدرسہ مظاہرعلوم سہارنپور ۲۴؍ربیع الثانی ۶۴ھ*
*الجواب صحیح: عبداللطیف غفرلہٗ مفتی مدرسہ مظاہرعلوم سہارنپور ۲۴؍ربیع الثانی ۶۴ھ*
======================
واللہ اعلم بالصواب
محمد مصروف مظاہری
@anwarulfuqaha
جانور کو ادھیا پر دینا
باسمہ سبحانہ تعالیٰ
الجواب وباللّٰہ التوفیق
زید کا عمر کو مادہ جانور پرورش کے لئے اس شرط پر دینا کہ جب اس کا بچہ پیدا ہوگا، تو وہ دونوں کے درمیان مشترک ہوگا اور مجھے کبھی کبھار تھوڑا بہت دودھ پینے کے لئے دینا شرعی طور پر اس طرح کا معاملہ ناجائز اور فاسد ہے؛ البتہ اس کے جواز کی یہ شکل ہوسکتی ہے کہ مالک اس جانور کی مناسب قیمت لگا کر نصف حصہ پرورش کرنے والے کے ہاتھ فروخت کردے، پھر اس کی قیمت معاف کردے، تو ایسی صورت میں جانوردونوں کے درمیان مشترک ہوگا اور اس کا بچہ اور دودھ بھی دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہوگا اور پرورش کرنے والے نے جو چارہ کھلایا ہے، اس کی نصف اجرت جو مالک پر لازم ہوئی پرورش کرنے والا اس کو معاف کردے۔
*(مستفاد: ایضاح النوادر/ ۱۱۵، فتاوی محمودیہ قدیم ۴/ ۲۶۰، ۱۲/ ۴۰۵، جدید ڈابھیل ۱۶/ ۵۹۵، ۵۹۹، بہشتی زیور ۵/ ۵۰،، امداد الفتاوی جدید ٨/٣٠١)*
واللہ اعلم بالصواب
محمد مصروف مظاہری
@anwarulfuqaha
باسمہ سبحانہ تعالیٰ
الجواب وباللّٰہ التوفیق
زید کا عمر کو مادہ جانور پرورش کے لئے اس شرط پر دینا کہ جب اس کا بچہ پیدا ہوگا، تو وہ دونوں کے درمیان مشترک ہوگا اور مجھے کبھی کبھار تھوڑا بہت دودھ پینے کے لئے دینا شرعی طور پر اس طرح کا معاملہ ناجائز اور فاسد ہے؛ البتہ اس کے جواز کی یہ شکل ہوسکتی ہے کہ مالک اس جانور کی مناسب قیمت لگا کر نصف حصہ پرورش کرنے والے کے ہاتھ فروخت کردے، پھر اس کی قیمت معاف کردے، تو ایسی صورت میں جانوردونوں کے درمیان مشترک ہوگا اور اس کا بچہ اور دودھ بھی دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہوگا اور پرورش کرنے والے نے جو چارہ کھلایا ہے، اس کی نصف اجرت جو مالک پر لازم ہوئی پرورش کرنے والا اس کو معاف کردے۔
*(مستفاد: ایضاح النوادر/ ۱۱۵، فتاوی محمودیہ قدیم ۴/ ۲۶۰، ۱۲/ ۴۰۵، جدید ڈابھیل ۱۶/ ۵۹۵، ۵۹۹، بہشتی زیور ۵/ ۵۰،، امداد الفتاوی جدید ٨/٣٠١)*
واللہ اعلم بالصواب
محمد مصروف مظاہری
@anwarulfuqaha